نئی نظم اور پورا آدمی: صرف نئے پڑھنے والوں کے لیے
عورت کی طرح شاعری بھی پورا آدمی مانگتی ہے۔ آپ عورت کو خوب صورت الفاظ سے خوش نہیں کرسکتے۔ صرف زیور، کپڑے اور نان ونفقے سے بھی نہیں۔ یہاں تک کہ صرف اس کام سے بھی نہیں جسے محبت کہتے ہیں اور جس کی حمدوتقدیس شاعری کا ازلی و ابدی موضوع ہے۔ عورت یہ سب چیزیں چاہتی ہے مگر الگ الگ نہیں۔ انہیں ایک وحدت ہونا چاہیے۔ ناقابل تقسیم وحدت۔ عورت کی طرح شاعری بھی اسی ناقابل تقسیم وحدت کی تلاش کرتی ہے۔ اس مضمون میں میں نئی نظم کی حقیقی قدروقیمت کو جانچنے کے لیے یہی پیمانہ استعمال کروں گا۔ کیا نئی نظم میں کہیں پورا آدمی بولتا ہے؟
لیکن یہ بات شاید آپ کو مضحکہ انگیز معلوم ہوئی ہو، آدمی ہمیشہ پورا آدمی ہوتا ہے۔ پون آدمی، آدھاآدمی، چوتھائی آدمی نہیں ہوتا۔ مجھے خود بھی یہ بات ہمیشہ بہت مضحکہ انگیز لگتی ہے۔ آدمی کسی بھی رتبے، حیثیت، طبقے اور پیشے کا ہو سکتا ہے مگر اسے ضرب تقسیم کے ذریعے کسر بنانا ایک نامعقول بات ہے۔ ہم سب اپنی ماں کے پیٹ سے پورے پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسا کیوں ہوتاہے کہ ہم لوئر ڈویژن کلرک کی حیثیت سے کچھ اور بن جاتے ہیں اور شوہر یا عاشق کی حیثیت سے کچھ اور۔ آپ کہیں گے کہ یہ صرف تقسیم کار کی حیثیتیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر بہت سے لوگوں میں اسی تقسیم کار سے آدمی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سیاسی آدمی، اخلاقی آدمی، مذہبی آدمی، انقلابی آدمی اسی قسم کے ٹکڑوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں انہیں کسری آدمی کہتا ہوں۔
کسری آدمی کائنات کی سب سے مضحکہ خیز مخلوق ہوتا ہے۔ مضحکہ خیز اورقابل نفرت۔ اسے دیکھ کر کائنات بکر قصاب کی دکان معلوم ہونے لگتی ہے۔ ۱۸۵۷سے پہلے اردو شاعری میں آپ کو یہ مضحکہ انگیز مخلوق مشکل سے نظر آئےگی۔ اسی لیے اس سے پہلے شاعری کی اصناف مرثیہ، قصیدہ، غزل، مثنوی وغیرہ تھیں۔ سیاسی شاعری، اخلاقی شاعری، مقصدی شاعری کی تقسیم ناپید تھی۔ شاعری کی یہ قسمیں کسری آدمی نے پیدا کیں۔ کیا میں کچھ بزرگوں کی توہین کر رہا ہوں؟
میرا خیال ہے حقیقت کے اظہار سے کسی کی توہین نہیں ہوتی سوائے ریاکاروں کے۔ اورجن بزرگوں کا حوالہ اس مضمون میں آئےگا، میں انہیں ریاکارنہیں سمجھتا، گووہ تاریخ کی ایک سفاک کروٹ کا شکار ضرور تھے۔ ۱۸۵۷سے پہلے ہند اسلامی تہذیب ایک وحدت تھی۔ غدر کے ہنگامے نے اسے چکناچور کر دیا۔ شاید اس کی اندرونی شکست وریخت غدر سے پہلے شروع ہو چکی تھی اور غدر صرف اس کا ایک خارجی مظہر تھا۔ غالب کا کلام اس کی ایک زبردست شہادت ہے۔ بقول شخصے ڈیڑھ جزو کے اس دیوان کا صرف مطلع اور مقطع ہی غائب نہیں ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں غائب ہوگئی ہیں جنہیں کھوکر ہم احیائے مذہب اور احیائے تہذیب کی ساری تحریکوں کے باوجود وہ نہیں بن پاتے جو ہم تھے۔ لیکن یہ بات شاید کچھ تفصیل چاہتی ہے۔
غالب وہ شاعر ہے جس کی ذات میں عقل، جذبہ، احساسات، عقیدے، وہ تمام قوتیں جو پہلے ایک تھیں اور ایک ہونے کے باعث کائنات اور اس کے فطری نظام سے ہم آہنگ تھیں، پوری طاقت سے ٹوٹ کر بکھر جانا چاہتی ہیں اور غالب اپنے شعور کی پوری قوت سے انہیں سمیٹے رکھنا چاہتا ہے۔ اس ہول ناک اور پراذیت پیکار، تصادم اور کش مکش سے وہ ناچتاہواشعلہ پیدا ہوتا ہے جسے غالب کا کلام کہتے ہیں۔ ہنداسلامی تہذیب غدر کے بعد ٹوٹ پھوٹ کر جتنی شکلیں اختیار کرےگی، اس کے سارے روپ میں اس آئینے میں پہلے ہی جھلک چکے۔ اب جو ٹکڑا اس آئینے کا اٹھائےگا اس میں اپنی صورت دیکھےگا۔ خواہ وہ اخلاق پرست حالی ہو یا جمال پرست بجنوری یا خودی پرست اقبال یامرگ پرست فانی۔ یہ سب غالب کی شکلیں ہیں اور غالب ان کی شکل ہے، اس لیے جب تک ہند اسلامی تہذیب کی شکست وریخت جاری رہےگی، غالب بھی زندہ رہےگا۔ غالب ان تمام پونے، آدھے، تہائی، چوتھائی آدمیوں کی اصل ہے جن کی کھیپ حالی کے ساتھ اور حالی کے پیچھے آئےگی۔ مگر غزل کاحالی تو خود پورا آدمی تھا۔
مجنوں گورکھ پوری صاحب نے لکھا ہے کہ ادب میں ارتداد کی دو افسوس ناک مثالیں ہیں۔ ٹالسٹائی اور حالی۔ لیکن حالی کاارتداد صرف ادبی نہیں تھا۔ حالی جب ادب میں بدلے توزندگی میں بھی بدل گئے۔ یہ بات ایک لحاظ سے حالی کے حق میں جاتی ہے۔ میں حالی کی تبدیلی سے خوش نہیں ہوں مگر ان کی عزت میرے دل میں کم نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے پر ایک مثال مولوی عبد الماجد دریابادی کی دیکھیے۔ مولوی صاحب فلم بینی کے شدید مخالف تھے۔ ایک مرتبہ خود فلم دیکھتے ہوئے پکڑے گئے۔ پوچھا گیا، ’’حضرت یہاں کیسے؟‘‘ فرمایا، ’’بدی کے مطالعہ کے لیے آیاہوں۔‘‘ واہ فلسفی شاہ۔ یگانہ صاحب انہیں یہی کہتے تھے۔ پتانہیں آپ کیا کہیں گے، میں تو اسے کسری آدمی کی نیرنگیاں کہتا ہوں۔ حالی میں یہ نیرنگی نہیں تھی۔
’’پردے بہت سے وصل میں بھی درمیاں رہے‘‘ کی شکایت کرنے والا حالی جب مولوی بناتو اسے سچ مچ اپنے نچلے دھڑپر شرم آنے لگی۔ ظاہر ہے اس کے بعد عورت کا عشق اپنے آپ بے حیائی اور بےغیرتی بن گیا۔ گوشت پوست کی محبوبہ کو چھوڑ کر حالی نے قوم کو محبوبہ بنالیا، بلکہ قوم کے ایک خاص تصور کو۔ مسدس اور حب الوطنی والی تمام نظمیں اسی محبوبہ کی شان میں لکھی گئی ہیں۔ کیوں کہ اس کا کام صرف اوپر کے دھڑ سے چل جاتاتھا۔ اوپر کے دھڑ پر مجھے ہمیشہ شیخ سدو کی حکایت یاد آ جاتی ہے۔
مشہور ہے کہ حضرت ناپاکی کی حالت میں اس طرح قتل ہوئے کہ غسل کے لیے پانی سرپر ڈال چکے تھے۔ چنانچہ سر جو پاک ہو چکا تھا، دفن کر دیا گیا اور دھڑ بھوت بن کر لوگوں پر سوار ہوتا پھرتا ہے اور بکرا مانگتا ہے۔ حالی کے بعد جو معاشرہ ہمارے یہاں تیزی سے ابھرا، اس کی اکثریت ایسے ہی افراد پر مشتمل تھی، جن کا دھڑ کچھ کرتا پھرے ان کے سر کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ حالی کی ’’سرمکتوم‘‘ والی اخلاقیات اسی معاشرے میں مقبول ہوئی۔ رہ گیا شیخ سدو کا بکرا تو وہ انہوں نے ۱۹۴۷ میں اکٹھا ہی وصول کر لیا۔
اس دور کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے جلدی جلدی دو ایک سطروں میں حالی کی اخلاقی، اصلاحی، سیاسی نظموں کو پھلانگتے ہوئے قوم پرستوں، اخلاق پرستوں اور فطرت پرستوں کی صف سے گزر جائیے۔ ان کی شاعری ہیئت کے نت نئے تجربات، بیان کی ندرتوں اور خیال کی نزاکتوں کا کتنا بڑاخزا نہ کیوں نہ ہو مگر اس خزانے کا ہر سکہ کھوٹا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اظہار کے بہت بڑے بڑے سانچے بنائے لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ اظہار کچھ نہیں کیا۔ ان سانچوں کی حیثیت ایسے مکانوں کی ہے جو اپنے اصلی مکینوں سے خالی پڑے سائیں سائیں کر رہے ہوں۔ الوؤں، چمگادڑوں اور ابابیلوں کے سوا ان سے اگر کسی کو کچھ دلچسپی ہو سکتی ہے تو آثار قدیمہ کے منتظمین کو۔ ارباب تحقیق کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ ان میں ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، سوائے ایک جوش صاحب کی شاعری کے جن کے کلام میں کسری آدمی کی تمام ٹوٹی پھوٹی ہوئی شکلیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوکر کسی نہ کسی طرح ایک وحدت میں تبدیل ہو جانا چاہتی ہیں، اور نہیں ہو سکتیں۔
لیکن اس مضمون میں چوں کہ میں صرف ۱۹۳۶ کے آس پاس شروع ہونے والی شاعری کاجائزہ لینا چاہتا ہوں اور جوش کی شاعری پر کچھ لکھنا ذراتفصیل بھی چاہتا ہے، اس لیے ان کا معاملہ کسی اور وقت پر چھوڑتا ہوں۔ ہاں تو اب ہم کہاں ہیں۔ ہم کہیں بھی ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے اختر شیرانی تک پہنچنا چاہیے۔
اختر شیرانی اردو شاعری کا سب سے پہلا رومانی شاعر ہے۔ اختر شیرانی صاحب کواس وقت اردو کاامرا ٔ القیس سمجھا جاتا تھا بلکہ کچھ اس سے زیادہ۔ ان کے ایک مجموعہ ٔ کلام پر ہمیں یہ الفاظ لکھے ملتے ہیں، ’’مشرق میں رومانی شاعری کے تین پیغمبر ہیں۔ ایک امرأ القیس دوسرا حافظ شیرازی اور تیسرااختر شیرانی۔ جس کی زبان حافظ کی تھی اور تخیل امرأ القیس کا۔‘‘ اس رائے کی تنقیدی اہمیت جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک مقبول عام رائے ضرور تھی۔ ذاتی طور پر یہ میری ایک کم زوری ہے (شاید عسکری صاحب کے اثر سے) کہ میں ٹھپے کے مستند نقادوں کی رائے کا اتنا لحاظ نہیں کرتا جتنا عام تصور کا۔ اس لیے مجھے اختر شیرانی کی یہ خصوصیت کہ انہوں نے اس وقت اپنا چراغ جلایا، جب اقبال اور جوش جیسے شاعر اپنے عروج پر تھے، مجھے ہمیشہ مرعوب کرتی رہتی ہے۔
اس سے بھی زیادہ مرعوب کن بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت اور شاعری دونوں میں افسانہ بن جانے کی صلاحیت موجود تھی۔ ان کی سلمیٰ اور ریحانہ اب تک ہماری شاعری کے نہ بھولنے والے کردار ہیں اور ان کے بعد آنے والے شاعروں میں مشکل سے کوئی شاعر ایسا ملےگا جس پر ان کی رومانیت کا اثر نہ ہو۔ یہ خصوصیات معمولی نہیں ہیں اور ادب کا کوئی طالب علم انہیں سرسری طور پر نظرانداز کرکے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن ان سب باتوں کے اعتراف کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ ان کی شاعری ہمیں اب اس طرح آسودہ کیوں نہیں کرتی۔ یہ سوال ہر شاعر کے بارے میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور جب بھی اٹھایا جائےگا، ہمیں خالص ادبی تنقید کی حدود سے گزرنا پڑےگا۔ کیوں کہ شاعری کامعاملہ بہر حال صرف ومحض شاعری سے آگے جاتاہے۔ آگے سے میری مراد ہے معاشرہ۔
اب اختر شیرانی کی مقبولیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارے معاشرے میں وہ نسل پیدا ہو چکی تھی جسے اختر شیرانی کی رومانیت میں وہ آئینہ مل گیا جس میں ان کی ذہنیت اور فطرت اپنی صورت دیکھ سکتی تھی۔ اور وہ چلا اٹھی کہ یہ ہے ہمارا شاعر۔ اس طرح اختر شیرانی کی شاعری کا تجزیہ دراصل ان کی نسل کا تجزیہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ذرا احتیاط سے اس آئینے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔
عنفوان شباب کی نفسیات بتاتے ہوئے مادام سموں دبوار نے ایک جگہ لکھا ہے کہ چوں کہ ہمارے زمانے کی عام فضا ایسی ہے کہ اس میں لڑکی ابتدا سے احساس کم تری کا شکار رہتی ہے۔ اس لیے آغاز شباب میں اپنے صنفی جذبات کا مرکز ایک ایسی شخصیت کو بنالیتی ہے جو اپنی عظیم الشان خوبیوں کے باعث اس کے احساس کم تری کی تلافی کر سکے۔ یہ شخصیت ہمیشہ غیر حقیقی اور تخیلی ہوتی ہے۔ اور ایسی خوبیوں کی حامل ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ کسی اور انسان میں نہیں پائی جاتیں۔ تمام انسانوں سے بلند وبرتر وہ ایک ایسے ’’شہزادے‘‘ کے خواب دیکھتی ہے جو آسمان کی مقدس بلندیوں سے صرف اسی کے لیے اترا ہے۔ اس طرح اپنی نظروں میں خود بھی ایک ’’شہزادی‘‘ کی طرح بلندوبرتربن جاتی ہے۔
لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ’’شہزادیوں‘‘ کی مصیبتیں عام عورتوں اور لڑکیوں سے بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ اس شہزادی کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہرآن بدلتا، رینگتا اور کلبلاتا ہوا بدن اسے خواب کی دنیا سے واپس کھینچ لانے کے لیے زور لگاتار رہتا ہے۔ ذرا اس ہماری شہزادی کی اذیت کا تصور کیجیے جو اپنے خوابوں میں ایک لطیف پیکرروحانیت کے سوااور کچھ باقی نہ رہی ہو۔ اور کم بخت بدن اسے یاد دلاتا رہے کہ اس کی دو ٹانگیں بھی ہیں۔ بہر حال شہزادی بننے کے لیے مصیبت تو جھیلنی ہی پڑتی ہے۔ یہ کوئی عام لڑکی تو ہے نہیں جس کا مرد کسی بھی گلی کوچے میں مل سکتا ہے۔ چنانچہ ’’شہزادی‘‘ اپنی تکمیل کے لیے سب سے پہلے اس ’’معمولی‘‘ لڑکی کی ٹانگیں ہی توڑتی ہے جس کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ خدا جانے کس گناہ کی سزا میں اسے اس کے ساتھ چپکا دیا گیا ہے۔ عنفوان شباب کی جھوٹی مذہبیت گناہوں کے ایسے ہی احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ کہ دراصل انہیں ابھی یہ پتانہیں ہوتا کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ لیکن یہ ایک جدا موضوع ہے۔
ہمیں فی الحال اپنی گفتگو صرف ’’شہزادی‘‘ تک محدود رکھنی چاہیے۔ اب شہزادی کی ایک خصوصیت تواحساس کم تری ہوئی جس کی تلافی خیالی برتری سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے اندر چند ایسی خصوصیات کا تصور کرتی ہے جو اتنی غیرمعمولی اور بلند و برتر ہیں کہ انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے خوابوں کے شہزادے کے۔ لیکن یہ شہزادہ اس وقت تک اسے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پورے وجود کو ایک خواب نہ بنا دے۔ اس لیے اپنے شعور کی پوری قوت سے اسے اس خواب کو اپنی پوری زندگی پر پھیلانا اور ان قوتوں سے لڑنا پڑتا ہے جو اس خواب کو توڑنے کے درپے ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی قوت خود اس کا اپنابدن ہوتا ہے۔ خاص طور پر بدن کے وہ حصے جنہیں جنسی اعضا کہا جاتا ہے۔ ’’شہزادی‘‘ اپنی ذات میں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اپنے بدن کو شکست نہ دے دے۔ بدن کو شعور سے خارج کرتے ہی وہ مکمل شہزادی بن جاتی ہے۔ اب آپ کاجی چاہے تو اس کا نام سلمیٰ رکھ دیجیے۔
لیکن یہاں شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ میں اختر شیرانی کی تلاش میں نکلا تھا اور ان کے بجائے سلمیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ مگر یقین کیجیے کہ میری نیت ٹھیک ہے۔ عسکری صاحب نے کہیں لارنس کا قول نقل کیا ہے کہ مرد دوبار پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کے پیٹ سے، دوسری مرتبہ اپنی عورت کے اندر سے۔ جس اختر شیرانی کی ہمیں تلاش ہے وہ اسی ’’سلمیٰ‘‘ کے اندرسے برآمد ہوگا۔ یعنی ایک ایسی مخلوق جس کا نچلا دھڑاس کی اپنی شہزادی کی طرح غائب ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری اسی اوپر والے دھڑوں کے جوڑے کی چوما چوٹی کی داستان ہے۔
اب اسے ان کی نسل کے ساتھ ملائیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ۱۹۲۲ سے ۱۹۳۶ کے درمیانی وقفے میں ہمارا معاشرہ اسی آدھے دھڑ کی عجیب وغریب مخلوق کا معاشرہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اختر شیرانی کی شاعری اسے امرأالقیس اور حافظ کی شاعری تو کیا ہے، تعجب ہے کہ قرآن کا جواب نہ معلوم ہوئی۔ اچھا تو اب ذرا اس ۱/۲ کی کسر والے جوڑے کے رومان کی تھوڑی سی تفصیل بھی ملاحظہ کیجیے۔ ’’صبح بہار‘‘ کی ایک نظم ہے ’’آج کی رات۔‘‘ نظم کی ابتدا دیکھیے،
کتنی شاداب ہے دنیا کی فضا آج کی رات
کتنی سرسبز ہے گلشن کی ہوا آج کی رات
کتنی فیاض ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات
کس قدر خوش ہے خدائی سے خداآج کی رات
مگر کیوں؟ جواب ہے، ’’کہ نظر آئے گی وہ ماہ لقا آج کی رات۔‘‘ اب ذرا اس کا تعارف بھی ملاحظہ کیجیے،
غائبانہ جو ہمیں نامے لکھا کرتی تھی
دور سے ہم پہ دل اپناجو فدا کرتی تھی
داداشعار جو ’’گم نام‘‘ دیاکرتی تھی
ہوکے بے پردہ جو پردے میں رہا کرتی تھی
ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یعنی یہ رومان یا عشق جو کچھ بھی ہے صرف تخیل کا کرشمہ ہے۔ سناتھا کہ عشق ہمیشہ دیدار سے نہیں پیدا ہوتا، کبھی گفتار سے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ دیداروگفتار کے بجائے صرف خطوط بازی سے چل رہاہے۔ خطوط بازی کاعشق جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، حقیقی عشق کی صرف ایک پیروڈی ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس میں حقیقی محبت کی اولین شرط ناپید ہوتی ہے۔ حقیقی محبت نام ہے دو بالکل مختلف چیزوں کے اپنے اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے میں سما جانے کا۔ من تو شدم تو من شدی۔ لیکن اس سے پہلے دونوں میں من وتو کا امتیاز ایک لازمی شے ہے۔ عشق کے پہلے تجربے کا اولین کرب اسی امتیاز کے احساس سے پیدا ہوتا ہے جس کا حاصل ہے شدید احساس تنہائی۔ بقول فراق،
اک فسوں ساماں نگاہ آشنا کی دیر تھی
اس بھری دنیامیں ہم تنہا نظر آنے لگے
دو مختلف وجودوں میں کامل نفسیاتی مطابقت کی جنگ کبھی کبھی اتنی ہول ناک ہوتی ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ کھیت رہتے ہیں۔ میر کی شاعری اسی جنگ کا رزمیہ ہے۔ لیکن یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس قسم کی نفسیاتی جدوجہد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلمیٰ اپنے نچلے دھڑ کو کاٹ کر مکمل شہزادی بن چکی ہے اور اپنے شہزادے کی تلاش میں ہے۔ جیسے ہی اختر شیرانی کی شاعری میں اسے اپنے شہزادے کی جھلک نظر آتی ہے، وہ اسے فوراً چھ پیسے والا لفافہ ڈال دیتی ہے کہ اوئی اللہ مار ڈالا۔ ادھر شہزادے صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں، فوراً اپنی شہزادی کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے،
جس کی نیرنگی سے افکار ہیں مدہوش مرے
جس کی الفت سے ہیں اشعار پراز جوش مرے
جس کی فرقت میں خیالات ہیں غم کوش مرے
جس کے جلووں سے تصور ہیں ہم آغوش مرے
کیارواں دواں مصرعے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جھٹاجھٹ ٹائپ رائٹر سے نکالے جا رہے ہیں۔ نہ کہیں کوئی نفسیاتی گرہ پڑتی ہے نہ جذبات اور الفاظ میں کسی کش مکش کا احساس ہوتا ہے۔ نہ لہجے میں کچھ سوچنے کا، محسوس کرنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ سچ مچ یہ اردو کی ’’خالص ترین‘‘ شاعری کا نمونہ ہے۔ خیر اس کا ذکر اگر موقع ملاتو آگے آئےگا، ابھی تو آپ ہمارے رومانی شہزادے کے جذباتی دنیا کی سیر کیجیے۔ میر صاحب کا ایک شعرہے،
وصل اس کا خدا نصیب کرے
میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ
اختر شیرانی صاحب اس ’’کیا کیا کچھ‘‘ کے مقابلے پر دعوی کرتے ہیں کہ ان کے ’’دل میں بھی‘‘ نت نئے جذبوں کی نشوونما ہو رہی ہے۔ ذرانت نئے جذبوں کی تفصیل دیکھیے،
داستان دل بے تاب سنائیں گے انہیں
آپ روئیں گے گلے مل کے رلائیں گے انہیں
خود ہی پھر رونے پہ ہنس دیں گے ہنسائیں گے انہیں
اور جرأت کی تو سینے سے لگائیں گے انہیں
کیا جیتا جاگتا جذباتی منظر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ’’بمبئی ٹاکیز‘‘ کی کوئی فلم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ دونوں دراصل ہیں بھی ایک ہی نسل کی چیزیں۔ تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ فلم کا نام سن کر علمی لوگ چڑ جائیں گے۔
خط، تصور، خواب اختر شیرانی کی شاعری میں باربار لوٹ کرآتے ہیں اور چوں کہ ان تینوں چیزوں سے محبوبہ کی عصمت میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اس لیے ان کے یہاں حسن کی اولیں صفت ہے، ’’معصومیت۔‘‘ خود جناب عاشق بھی کچھ کم معصوم نہیں ہیں، اس لیے دونوں کی ملاقات میں ’’اللہ ملائی جوڑی‘‘ کا مزہ آتا ہے۔ ملاقات سے پہلے عاشق کے دل میں مندرجہ ذیل معصوم حسرتیں پیدا ہوتی ہیں،
یوں تو ہر طرح ادب مد نظر رکھنا ہے
حسرت دل کا لحاظ آج مگر رکھنا ہے
بے خودی دیکھ تجھے میری خبر رکھنا ہے
نازنیں قدموں پہ یوں ناز سے سر رکھنا ہے
آج کی رات اف، او میرے خدا آج کی رات
یہ نظم کاخاتمہ ہے
آج کی رات اف، او میرے خدا آج کی رات! پت انہیں اس مصرعے کی صوتی فضا کس قسم کی ہے لیکن مجھے ہمیشہ اسے پڑھ کرنہ جانے کیوں میراجی کا ایک مصرع یاد آ جاتا ہے، ہاتھ آلودہ ہے، نم دارہے، دھندلی ہے نظر، ذراآپ بھی دیکھیے کہیں نظم کا خاتمہ ماسٹر بیشن تونہیں ہے؟
جس زمانے میں مذکورہ شہزادے اور شہزادیاں معصوم محبت کا یہ دلچسپ کھیل کھیلتے ہیں، اس وقت ان کے نچلے دھڑ کی عملی دلچسپیاں بھی اسی قسم کے کاموں میں ہوتی ہیں لیکن وہ انہیں شعور میں نہیں آنے دیتے۔ کیوں کہ جنس ان کے لیے ایک مکروہ اور گھناؤنے فعل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح وہ مصنوعی معصومیت پروان چڑھتی ہے جس کی قصیدہ خوانی اختر شیرانی کی نظموں کا محبوب موضوع ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ محبوبہ کا ذکر کریں اور اس کے ساتھ معصوم کا لفظ نہ لگائیں۔ معصومیت کا یہ کا بوس ذہنی گندگی کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ منٹو کہتا تھا جب کوئی عورت مارے معصومیت کے مجھے بھائی کہتی ہے تو میں فوراً اس سے انگیا کا ناپ پوچھتا ہوں۔ لیکن منٹو پورا آدمی تھا اور اختر شیرانی صرف اوپر کا دھڑ ہے۔ پورے آدمی کے ساتھ میں کہیں اوپر کائناتی ہم آہنگی کا ذکر کر چکا ہوں۔ پورا آدمی جب اپنی حقیقی محبوبہ میں جوخود بھی پوری عورت ہوتی ہے، جنسی تجربے کے ذریعے سما جاتا ہے تو محبوبہ اور کائنات ایک چیز بن جاتی ہے۔ فراق نے کیا شعر کہا ہے،
تارے بھی ہیں بیدار زمیں جاگ رہی ہے
پچھلے کو بھی وہ آنکھ کہیں جاگ رہی ہے
لیکن کسری مخلوق اپنی مسخ شدہ فطرت کے باعث (نفس انسانی) کے اس عمیق ترین تجربے سے محروم رہتی ہے۔ آل احمد سرور صاحب نے جوش کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں فطرت صرف سیج کا کام کرتی ہے۔ اختر شیرانی کے ہاں بھی فطرت کا یہی مصرف ہے،
آسماں پر چھا رہا ہے ابرپاروں کا ہجوم نوبہاروں کا ہجوم
آہ یہ رنگین آوارہ نظاروں کا ہجوم کوہساروں کا ہجوم
ننھی ننھی بوندیں گرتی ہیں حجاب ابر سے یانقاب ابر سے
چھن رہا ہے قطرے بن بن کرستاروں کا ہجوم نور پاروں کا ہجوم
آہ یہ مخمور آنکھیں مست سی بے خواب سی نیند میں بےتاب سی
جن سے چھلکا پڑ رہا ہے حشر پاروں کا ہجوم فتنہ زاروں کا ہجوم
ابر پارے، کوہسار، نورپارے، مہتاب، سبزہ زار اور ان سب کے درمیان۔۔۔ سلمیٰ ستارے، چاند، مست پھول، کھلی چاندنی، سنہری دھوپ، طائران گلشن، شفق، شمع، آئینہ، عروس برق، غرض کائنات کی ہر چیز اسے حیرت سے دیکھتی ہے کیوں کہ وہ کائنات کی عجیب ترین مخلوق ہے۔ آدھے دھڑ کی عورت! مگر اختر شیرانی کو اس کا احساس نہیں۔ وہ خود بھی اسی جیسا ہے۔ فطرت کی اس حسین سیج پر اوپر والے دھڑوں کا یہ دلچسپ جوڑا گلے میں بانہیں ڈال کر لیٹےگا جیسے دو سہیلیاں لیٹتی ہیں۔ اور پھر وہ سب کچھ ہوگا جو ایسی نازک ملاقاتوں میں ہوتا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کے تقدس، ملکوتیت اور پاکیزگی پر خدانخواستہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔
یاد رہے کہ فراق کی’’ترے جمال کی دوشیزگی نکھرآئی‘‘ والی بات اس سے قطعی مختلف ہے۔ فراق کے محبوب میں یہ پاکیزگی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی فطرت، اپنے پورے وجود کو قبول کر لیتا ہے اور جنس اس کے لیے کوئی ناپاک، گندی یاقابل تحقیر چیز نہیں رہتی۔ اختر شیرانی کی پاکیزگی اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ اس کی لفظی خوب صورتی پر نہ جائیے۔ اس سے ’’اخلاقیات‘‘ کی ایسی قدریں پیدا ہوتی ہیں جن سے تہذیب کی ساری بنیادیں ہل جائیں۔ اختر شیرانی کی شاعری کے اس حصے پر پہنچ کر ہرحساس دل کو خوف، غصے اور نفرت سے کانپ اٹھنا چاہیے۔
سلمیٰ اور اختر شیرانی کے ملاپ کا نقشہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اختر شیرانی اسے شاعرانہ زندگی کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کا نصب العین ہونا چاہیے۔ جو کچھ اس کے برعکس ہے، وہ بدمذاقی ہے۔ اختر شیرانی کی کائنات کے خیروشر انہیں دو لفظوں سے متعین ہوتے ہیں۔ عورت سے رومانس لڑانا شاعرانہ بات ہے۔ عورت سے جنسی ملاپ کرنا بدمذاقی ہے۔ آپ اسے مذہب یا معاشرے کی مسلمہ اخلاقی اقدار سے خلط ملط نہ کیجیے۔ جنسی ملاپ کے معنی صرف ناجائز تعلقات کے نہیں ہیں۔ گو ناجائز تعلقات بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے شاعری کی حقیقی قدروقیمت پر کوئی اثر نہیں پڑےگا، سوائے اس اثر کے جو ایسے غیراخلاقی افعال سے خود شاعر پر مرتب ہو۔ اختر شیرانی کی رومانی اخلاقیات ناجائز تعلقات کی نہیں بلکہ خود جنسی ملاپ کی مخالف ہے، خواہ وہ کسی صورت میں بھی ہو۔ یہ میں کوئی قیاسی گدا نہیں لگا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ صاف بات تو اختر شیرانی نے اپنی پوری شاعری میں کہیں کی ہی نہیں۔ نظم ذرا طویل ضرور ہے مگر پوری توجہ سے ملاحظہ کیجیے،
اے کہ تھا انس تجھے عشق کے افسانوں سے
زندگانی تری آباد تھی رومانوں سے
شعر کی گود میں پلتی تھی جوانی تیری
تیرے شعروں سے ابلتی تھی جوانی تیری
رشک فردوس تھ اہرحسن بھراخواب ترا
ایک پامال کھلونا تھا یہ مہتاب ترا
نکہت شعر سے مہکی ہوئی رہتی تھی سدا
نشۂ فکر میں بہکی ہوئی رہتی تھی سدا
شرکت غیر سے بیگانہ تھے نغمے تیرے
عصمت حور کا افسانہ تھے نغمے تیرے
گویا سلمی کی طرح یہ بھی انتہا درجے کی رومانی مگر اتنی ہی شدت سے ’’تقدس مآب‘‘ ہیں۔ یعنی رومانس تو چھتیس لڑا ڈالے ہیں مگر کبھی اس بات کی مرتکب نہیں ہوئیں جسے اختر شیرانی بد مذاقی کہتے ہیں۔ اب نظم کا گریز ملاحظہ کیجیے،
اب گوارا ہوئی کیوں غیر کی صحبت تجھ کو
کیوں پسند آ گئی ناجنس کی شرکت تجھ کو
عفتیں مٹ کے جوانی کو مٹا جاتی ہیں
پھول کمھلاتے ہیں، کلیاں کہیں کمھلاتی ہیں
ہوس آلودہ ہوئی پاک جوانی تیری
غیر کی رات ہے اب اور کہانی تیری
تیرگی حرص کی، حوروں کو بھی بہکا ہی گئی
تیرے بستر پہ بھی آخر کو شکن آہی گئی
دیکھا آپ نے؟ کیا رجزیہ آہنگ ہے۔ معاف کیجیے، میرا مطلب ہے جیسا کچھ رجزیہ آہنگ ایک بےچارے رومانی میں ہو سکتا ہے۔ اختر شیرانی اتنے جوش میں ذرا کم ہی آتے ہیں۔ مگر اس عورت سے گناہ ہی ایسا زبردست سرزرد ہوا ہے۔ کم بخت شاعرانہ زندگی چھوڑ کر بدمذاقی کر بیٹھی ہے۔ یعنی بےچاری نے نکاح کر لیا ہے۔ نظم کاچعنوان ہے،’’ایک شاعرہ کی شادی پر۔‘‘ اورچاوپر سے ہمارے شاعر رومان نے نوٹ بھی لکھ مارا ہے کہ ’’جس کا دعوی تھا کہ وہ دنیا میں صرف شاعرانہ زندگی گزارنے آئی ہے۔‘‘ رومانیت کے پیغمبر کو ظاہر ہے کہ یہ ارتداد کیسے برداشت ہو سکتا ہے۔ وہ تو عورت کو شہزادی، حور،، پری، سلمی، ریحانہ اوراسی قسم کی ساری بلیات کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، عورت کے روپ میں نہیں۔ عورت کی حیثیت ان کے نزدیک بربط نفس کے فحش ترانے سے زیادہ نہیں،
اب نہیں تجھ میں وہ حوروں کی سی عفت باقی
حور تھی تجھ میں، گئی، رہ گئی عورت باقی
ہاں وہ عورت جسے بچوں کا فسانہ کہیے
بربط نفس کا اک فحش ترانہ کہیے
رومانیت کی معصومیت بالآخر اسی شیطنت تک پہنچتی ہے۔ وہ عورت تو کیا ماں کا احترام بھی نہیں کر سکتی اور اس طر ح پوری گھریلو زندگی سے متنفر اور انسانیت اور تہذیب کی بنیادی قدروں کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ عورت ماں، بیوی اور حقیقی زندگی کے بجائے حور، پری، سلمیٰ اور شاعرانہ زندگی کی دل دادہ ہوتی ہے اور نہیں جانتی کہ عورت کی یہ ساری مصنوعی شکلیں کتنی ہی خوب صورت کیوں نہ ہوں، ہیں در اصل شیطانی شکلیں۔
۱۹۳۶کے آس پاس کے زمانے میں ہندوستان کے بطن میں کیسے کیسے شیطانی فتنے پروان چڑھ رہے تھے، انہیں دیکھنے کے لیے صرف اس ’’پیغمبر رومان‘‘ کی شاعری کو پڑھ لینا کافی ہے۔ اختر شیرانی بہت بڑا شاعر ہوتا اگروہ ان فتنوں کا پردہ فاش کرتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اس کی صلاحیت بھی تھی۔ اس کے آخری مجموعے ’’شہرود‘‘ میں فکاہات کے عنوان سے اس کی چند طنزیہ نظمیں جمع کی گئی ہیں، جنہیں ایک نظر دیکھ کر ہی اس کے امکان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان نظموں میں بیشتر نظمیں عورتوں کے اس رجحان پر ہیں کہ وہ مردوں کی طرح بال کٹوانے لگی ہیں اور انہیں نسوانیت کے بجائے مردوں کا بہروپ بھرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ معاشرے کے اس رجحان پر سب سے پہلے شاعر رومان ہی کی نظر گئی۔ صرف بیج بونے والا ہی تاڑتا ہے کہ اس کے درخت میں کیسا پھل لگا ہے۔ اختر شیرانی کے بوئے ہوئے درخت کا پھل اب ان کے سامنے تھا اور کتنا زہریلا پھل۔۔۔ ایک مختصر سی نظم دیکھیے،’’مرد وعورت کی یک رنگی۔‘‘
کل شب کو تھیں اک ہال میں جلوہ کناں حوروپری
یامحو رقص ونغمہ تھے صد ہابتان آزری
تہذیب نو کے رنگ سے لبریز تھی ہر اک ادا
ملبوس کی عریانیاں، انداز کی عریاں گری
تھے زلف و گیسو کی جگہ مردانہ فیشن سر کے بال
وہ تھیں کہ صد ہامغ بچے مست شراب دلبری
یہ دیکھ کر میں نے کہااک شوخ صبر آشوب سے
کیوں کر گوارا ہے تجھے یہ گیسوؤں کی ابتری
اس ’’شوق صبر آشوب‘‘ کا جواب بھی سننے کے قابل ہے، یہ کہتی ہے،
مردانہ فیشن سے غرض اس کے سوا کوئی نہیں
تاکس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری
شاعر رومان کو کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی اپنی رومانیت کی اولاد ہے۔ عورت کو یا تو مرد اپنے اندر گم کرکے اپنا جیسا بنا لے ورنہ پھر وہ دوسرے طریقے اختیار کرتی ہے۔ کسی رومان پرست پر اس سے بڑا طنز اور کیا ہو سکتا ہے کہ عورت مردانہ کپڑے پہن کر اس سے کہے کہ لو اب ہم تم ایک جیسے ہیں۔ رومانیت کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ ’من تو شدم تو من شدی‘ کا مسئلہ اسی طرح حل ہو۔ ہندوستان واقعی ۱۹۴۸تک کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ اختر شیرانی کی رومانیت کی یہ حقیقی اولاد اب بڑھتی ہی جائےگی۔ یہاں تک کہ ۱۹۶۱ میں حکومت اور عوام کو مل کر ٹیڈی گرلز کے خلاف مہم چلانی پڑےگی۔ بہر حال یہ کچھ کم نہیں کہ اختر شیرانی نے اسے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ وہ اگر اور زندہ رہتا تو ممکن ہے کہ اس کا یہی رنگ ترقی کرتا اور اردو شاعری کو سچ مچ ایک بڑا شاعر مل جاتا۔
مگر دوست! تم نے بہت دیر کر دی۔ تم نے اپنی جوانی کا بہترین حصہ ایک ایسی گھناؤنی، غلیظ اور قابل نفرت مخلوق کا سجا بناکر ہمارے سامنے پیش کرنے میں صرف کر دیا جو عورت کی ادھوری او ر مسخ شدہ شکل ہے اور جب تمہیں اس کا احساس ہوا اس وقت تم اپنی سلماؤں اور ریحاناؤں کے غم میں شراب پی پی کر خدا کی بخشی ہوئی اس سب بڑی نعمت کو تباہ کر چکے تھے جسے زندگی کہتے ہیں اور یہ تمہاری آخری سانسیں تھیں۔ اچھا تو جاؤ، زندگی کی طرح ادب میں بھی رحم کا کوئی خانہ نہیں ہے۔
اب اپنی ہی جیسی مخلوق کے ساتھ خوش رہو۔ وہ تمہیں آسمان پر چڑھائیں گے۔ پیغمبر رومان کہیں گے۔ تمہیں امرأالقیس اور حافظ کا ہم پلہ قرار دیں گے اور جب تمہاری پیدا کی ہوئی مخلوق کا نچلا دھڑ معاشرے پر شیخ سدو کی طرح سوار ہو جائےگا تو بدمزہ ہوکر چبائے ہوئے نوالہ کی طرح تمہیں کسی گندی نالی میں تھوک دیں گے، اور ۱۹۶۱میں ایک میرے جیسے معمولی مضمون نگار کو تم پر مضمون لکھتے ہوئے معذرت کے انداز میں اس سوال کے جواب پر غور کرنا پڑےگا کہ تم جو اتنے چھوٹے ہو، ایک زمانے میں اتنے بڑے کیسے سمجھے جاتے تھے؟ سنا میرے شاعر رومان!
غدر کے بعد ۱۹۳۶ تک ہندوستانی معاشرے میں شیخ سدو کے بھوتوں کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ جب اختر شیرانی کی مصنوعی تقدس والی رومانیت کے ملبے کے نیچے سے میراجی اور ن م راشد آہستہ آہستہ رینگ کر باہر نکل آئے۔ میں نے فیض کا نام یہاں قصداً نہیں لیا ہے۔ فیض اپنے ان دونوں معاصرین سے بالکل مختلف چیز ہیں۔ اس لیے ان کا ذکر اپنے مقام پر آئےگا۔ جدید نظم کے اماموں کی حیثیت سے راشد اور میراجی کی جو تاریخی حیثیت ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ اس شاعری سے اتفاق کریں یا اختلاف، اسے اپنے ذوق کے مطابق پائیں یانہ پائیں لیکن شاعری کا معاملہ ذاتی پسند ناپسند سے آگے جاتا ہے۔ آپ کی زبان کی تاریخ میں شاعری کی ایک نئی روایت قائم ہو گئی۔ اب ایک آدمی یا ہزار آدمی اسے تاریخی تسلسل سے خارج نہیں کر سکتے۔ بالفرض یہ روایت آگے نہ بھی جائے جیسا کہ بعض ناقدوں کا خیال ہے، تو بھی تاریخ میں اس کی جگہ متعین ہو گئی۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ اتنے دو ٹوک انداز میں منقطع ہو گیا ہو۔
جہاں تک بے قافیہ اور آزاد نظموں کے استعمال کاتعلق ہے، شاعروں کی ایک خاصی بڑی تعداد اس میں پہلے بھی کام کررہی تھی اور اب بھی کررہی ہے بلکہ لاہور کی نئی نسل نے تو ازسر نوپورے جوش و خروش سے اسی سلسلے کوآگے بڑھانے کی مہم شروع کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ نئی نظم کا یہ سلسلہ جب تک چلتا رہےگا، خواہ دس برس یا ہزار برس، راشد اور میراجی کو اپنی جگہ سے ہلانے والا کوئی نہیں۔ اولاد لاکھ ناخلف ہو اور لاکھ علم بغاوت بلند کرے مگر یہ معاملہ تو سلسلۂ نسب کا ہے۔ بقول شخصے، ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں جس کا ہاتھی اس کا ناؤں۔ اور اس سے کون انکار کرےگا کہ نظم جدید کا ہاتھی سب سے پہلے میراجی اور راشد نے نکالا۔ ویسے ان کا ہاتھی ایسے چپ چپاتے بھی نہیں نکلا تھا۔ ہمیں تو یہ یاد ہے کہ پورا ہندوستان دیکھنے آیا تھا۔
ادھر کچھ نوجوانوں سے بات چیت کرنے اور کراچی اور لاہور کی نئی نسل کا ایک آدھ مضمون پڑھنے سے مجھے کچھ ایسا اندازہ ہوا جیسے یہ لوگ اپنے پیش روؤں کا ذکر یا تو کچھ تحقیر سے کرتے ہیں یا پھر قدرے سرپرستانہ انداز میں۔ میری رائے چھپے تومیں اس میں بھی کچھ حرج نہیں سمجھتا۔ آخر ہمارے انتظار حسین نے لکھ ہی دیا ہے کہ نوجوانوں کو بزرگوں کا نام صرف زبانی ہی نہیں، باقاعدہ تحریری طور پر بھی پوچھنا چاہیے۔ کبھی کبھی نوجوانوں کواپنا اثبات کرنے کے لیے بزرگوں کا انکار کرنا ہی پڑتا ہے لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ بزرگوں کے انکار میں اگر آپ سچ مچ، پرخلوص ہو جائیں تو بعض اوقات اپنے معنی بھی مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ یعنی چھیڑ چھاڑ میں تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن ویسے اندر ہی اندر یہ سلسلہ قائم رہے تو اپنے ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔
یہاں تک تو تھا راشد اور میراجی کی تاریخی اہمیت کا مسئلہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری کا جو بھی معیار قائم کریں، اس پر یہ دونوں شاعر اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں کہاں تک پورے اترتے ہیں۔ اور اس طرح ان کا شاعرانہ مقام کیا بنتا ہے؟ بہت سے لوگ انہیں مختلف معیاروں سے پرکھیں گے اور بہر حال جو نتیجہ بھی وہ نکالیں، اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ میں بھی تنہا اپنی ہی ذمہ داری پر انہیں اپنے معیار سے پرکھنا چاہتا ہوں۔ کیاان کی نظموں میں ’’پورا آدمی‘‘ بولتا ہے؟ اختر شیرانی کے تجزیے میں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ جو کچھ بھی دیں، اس کا تعلق معاشرے سے ضرور ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ راشد اور میراجی کے بارے میں ہم جو بھی جواب دیں گے وہ ان کی نسل کے بارے میں بھی ہمیں بہت کچھ بتائےگا۔
راشد کے سلسلے میں، میں یہ بات خاص طور پر اس لیے جتانا چاہتا ہوں کہ حیات اللہ انصاری صاحب نے، جن کی کتاب ’’ن م راشدپر‘‘ بعض حلقوں میں راشد پر حرف آخر کی حیثیت سے پڑھی گئی، ان کی شاعری کے سماجی، تاریخی، ادبی پس منظر کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہاں میں آپ کو پورا حق دیتا ہوں کہ آپ انتہادرجے کی عینیت پرستی سے کام لے کر تیوری چڑھاتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ شاعری وہ ہے جو اپنے اثر کے لیے کسی پس منظر یا پیش منظر کی محتاج نہ ہو۔ لیکن ساتھ ہی مجھے بھی بہ صدادب یہ گزارش کرنے کا حق دیجیے کہ تب تو ۱۸۵۷ کے بعد کا کوئی بھی شاعر مشکل سے جمےگا۔ یہاں تک کہ کسی حد تک اقبال بھی بلکہ دراصل پوری اردو شاعری میں صرف میر اور غالب ہی رہ جاتے ہیں، جیسا کہ بعض مدمغ ارباب نقدونظر کا خیال ہے۔ لیکن یہاں میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ شاعری کو پڑھنے پڑھانے کے بہت سے انداز، ڈھب اور طریقے ہیں، اور ہمیں وقتًا فوقتًا انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا چاہیے۔ میں اس بات پر خاص طور پر اس لیے زور دینا چاہتا ہوں کہ ہماری شاعری کی موجودہ حالت میں میرے ناقص خیال کے مطابق ہمارے تنقیدی رویوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ شاعری کو صرف اپنے جذبات کی نکاسی کے لیے پڑھنے کا آخری نتیجہ یہی ہے کہ ہم شاعری کو اخبار کی طرح پڑھنے لگیں یعنی تازہ خبر کے علاوہ اور جو کچھ ہے، بےکار ہے۔
خیر ذکر تھاحیات اللہ انصاری کی کتاب کا۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ ایک تو راشد کی شاعری کو راشد کی ذاتی ڈائری کی حیثیت سے پڑھا۔ شاعری ذاتی ڈائری سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے ’’مباشرت‘‘ کا مکمل طریقہ توانہوں نے امرأالقیس کے اشعار اور ایڈلر کے حوالوں سے سیکھ لیا مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آدمی اتنی ہی صحیح مباشرت ہر دور میں کر سکتا تو جناب ایڈلر بلکہ ان کے بھی باوا جناب فرائیڈ کے پیدا ہونے کی کوئی سبیل مشکل ہی سے نکلتی۔ معاملہ تو سارا یہ ہے کہ معاشرے کی بھیانک قوتیں فرد کو اندر سے توڑتی پھوڑتی رہتی ہیں۔ ورنہ جن ذہنی اور نفسیاتی امراض کی فہرست جناب انصاری نے گنوائی ہے، انہیں کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں پیدا ہوتا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعر کو اپنی جگہ پورا آدمی ہونا چاہیے یا کم از کم پورا آدمی بننے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ وہ معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کا صحیح نباض نہ بن سکےگا۔ اس کے باوجود ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ شاعر بھی بہرحال اسی معاشرے کا ایک جزو ہوتا ہے اور ہم اس پر اتنے مطلق انداز میں کوئی معیار نہیں عائد کر سکتے۔ پتا نہیں میر صاحب کو اگر ان کے زمانے میں سے بہتر وقت ملتا تو وہ کیسی شاعری کرتے۔ اس طرح شاعری کا بنیادی مسئلہ اتنارہ جاتا ہے کہ فرد پر معاشرے میں جو کچھ گزری ہے اور وہ جس طرح بھی اس کے پورا آدمی بننے میں حائل ہے، شاعر اسے مقدور بھر شعور میں لاتا رہے۔
البتہ یہ دیکھنا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں شاعر کسی مسخ شدہ جبلت، جذبے یا احساس کو تو بنا سنوار کر ہمارے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے کیوں کہ اس طرح وہ شاعری کے بجائے ایک ایسا جذباتی ملغوبہ ہمارے حوالے کرتا ہے جو ہمارے ذہنی اور نفسیاتی امراض میں اور اضافے کاباعث بنتا ہے جیسا کہ ہم ابھی اختر شیرانی کی شاعری میں دیکھ چکے ہیں۔ اس لمبی چوڑی اور شدید قدرے خشک تمہید کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہوں، راشد اور میراجی کی شاعری۔ میں صرف اپنی سہولت کے لیے راشد کو پہلے لیتا ہوں۔
راشد کی شاعری کے ابتدائی حصے پر اختر شیرانی کا اثر نمایاں ہے۔ گو’’ماورا‘‘ کے تعارف نویس نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ رومانیت کا اعتراف بہر حال موجود ہے۔ خدا کا شکر اس لیے کہ رومانیت کے اس اثر کے بغیر راشد کی شاعری کے پورے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ رومانیت کے اثر کے معنی یہ ہیں کہ راشد اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ شاعری ایسے آدمی کی نہیں ہے جو پہلے سے پورا آدمی ہو بلکہ ایک ایسے آدمی کی شاعری ہے جس کی نفسیات میں ایک دراڑ پڑ چکی ہے مگر وہ اسے چھپانے یا اختر شیرانی کی طرح سجانے سنوارنے کے بجائے اسے پر کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔
اب اسے شاعر کی ذات سے الگ لے جاکر معاشرے پر منطبق کیجیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شاعری ایسے لوگوں کے لیے ہے جورومانیت کی گھناؤنی نالی میں گرنے کے بعد اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گویا معاشرے کے اس حصے کی صحت کا دارومدار جس پر رومانیت کی لعنت مسلط ہو چکی ہے، راشد کی کا میابی پر ہے۔ راشد کامیاب ہو گئے تو وہ بھی اس نالی سے نکل آئیں گے ورنہ پھر شیخ سدو کا بکرا تو دینا ہی پڑےگا۔ آئیے اب راشد کی کوشش کا بغور مطالعہ کریں۔ ’’ماورا‘‘ کی پہلی نظم کا عنوان ہے،’’میں اسے واقف الفت نہ کروں۔‘‘ نظم کا موضوع عنوان ہی سے ظاہر ہے۔ عاشق اپنی محبوبہ سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کرتا۔ وجہ خود نظم میں ملاحظہ کیجیے،
سوچتاہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ
میں ابھی اس کو شناسائے محبت نہ کروں
روح کو اس کی اسیر غم الفت نہ کروں
اس کو رسوا نہ کروں، وقف مصیبت نہ کروں
سوچتاہوں کہ جلادے گی محبت اس کو
وہ محبت کی بھلاتاب کہاں لائےگی
خود تو وہ آتش جذبات میں جل جائےگی
اوردنیا کواس انجام پہ تڑپائےگی
سوچتاہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ
میں اسے واقف الفت نہ کروں
یہ نظم کے پہلے اور آخری بند ہیں۔ غیرمناسب نہ ہوگا اگر ہم ان کا مختصر تجزیہ کر لیں۔ پہلے بند کے پہلے مصرعے میں محبوبہ کو سادہ و معصوم کہا گیا ہے۔ اختر شیرانی کی معصوم محبوبہ کو یاد کیجیے، یہ بھی اسی کی ہم فطرت ہے۔ اپنے ہی خوابوں میں ڈوبی ہوئی شہزادی جو اپنی جنس سے بے خبر ہے۔ اب اختر شیرانی اور راشد کے رویوں کو ایک دوسرے کے تقابل میں رکھ کر دیکھیے۔
اختر شیرانی کے لیے اس کی شہزادی یا سلمیٰ ایک ایسی ہستی ہے جس پر وہ غائبانہ تعارف ہی میں لہلوٹ ہو جاتا ہے۔ ادھر وہ بھی تیار ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کا شہزادہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ پہلے تو رسماً دوچار خطوط میں چھیڑ چھاڑ چلتی ہے اور پھر ملاقات کی ٹھہرتی ہے۔ ملاقات میں بھی سوچنے سمجھنے کا کوئی کام نہیں، کیوں کہ ان کی محبت کا آغاز اور انجام پہلے سے متعین چیزیں ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ ایک دوسرے کو ’’شہزادہ شہزادی‘‘ کہہ کر پکاریں گے اور پھر فطرت کی سجائی ہوئی سیج پر سہیلیوں کی طرح گلے میں بانہیں ڈال کر لیٹیں گے۔ اور اس پاک محبت پر ان کا خدا آسمان سے ان کے اوپر پھول برسائےگا۔
اس کے برعکس راشد صاحب کا معاملہ شروع ہی سوچ بچار سے ہوتا ہے۔ راشد اپنی محبوبہ کی اصلیت بھی جانتا ہے اورمحبت کی بھی۔ اسے معلوم ہے کہ محبت صرف گل بھیاں کرنے کا نام نہیں ہے، نہ دامن میں پھول، چاند، ستارے وغیرہ لے کر محبوبہ کو پیش کرنے کا۔ وہ جانتا ہے کہ محبت کا معاملہ دامن کے نیچے جاتا ہے۔۔۔ اور دامن کے نیچے جاتے ہی معاشرے کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ابتدا ہے۔ اس کے بعد بات معاشرے سے قانون، قانون سے اخلاق، اخلاق سے مذہب اور مذہب سے خدا تک پہنچتی ہے۔ چوں کہ یہ مسائل پورے آدمی کے ہیں اس لیے راشد سوچتا ہے۔
اب نظم کا لب ولہجہ دیکھیے۔ مصرعے اختر شیرانی کی طرح رواں دواں نہیں ہیں۔ ان کے پیچھے جذبات کی کش مکش کا پتا چلتا ہے۔ یہ نسبتاً آہستہ خرام اور کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان میں نفسیاتی پیچیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک ہی نظر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رومانیت سے نکل کر آگے جانے والے کی شاعری ہے، پہلی نظم کے بعد بیچ کی چند ناقابل ذکر اور مشقیہ نظموں کو چھوڑ کر آگے بڑھیے۔ ’’مکافات‘‘ میں راشد صاحب کے ’’میں‘‘ کا حال دیکھنے کے قابل ہے،
گزرگئی ہے تقدس میں زندگی میری
دل اہرمن سے رہا ہے ستیزہ کار مرا
کسی پہ روح نمایاں نہ ہو سکی میری
رہا ہے اپنی امنگوں پہ اختیار مرا
دبائے رکھا ہے سینے میں اپنی آہوں کو
وہیں دیا ہے شب وروز پیچ وتاب انہیں
زبان شوق بنایا نہیں نگاہوں کو
کیا نہیں کبھی وحشت سے بے نقاب انہیں
خیال ہی میں کیا پرورش گناہوں کو
کبھی کیانہ جوانی سے بہرہ یاب انہیں
یہ مل رہی ہے مرے ضبط کی سزا مجھ کو
کہ ایک زہر سے لبریز ہے شباب مرا
اے کاش چھپ کے کہیں اک گناہ کر لیتا
حلاوتوں سے جوانی کو اپنی بھر لیتا
گناہ ایک بھی اب تک نہ کیوں کیا میں نے؟
راشد کا آدمی رومانیت سے کس طرح گتھم گتھاہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اس نظم میں اوپر کا دھڑ نیچے کے دھڑ سے ملنے کے لیے بے تاب ہے تاکہ ایک مکمل وحدت بن جائے۔ مگر رومانیت نے اوپر کے دھڑکو بتا رکھا ہے کہ نیچے کا دھڑ ناپاک ہے۔ اس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ابھی مسئلے کو اخلاقیات سے نہ الجھائیے۔
اخلاقیات آدمی کو گناہ سے روکتی ہے، پورا آدمی بننے سے نہیں بلکہ سچی اخلاقیات تو پیدا ہی پورے آدمی کے کرب سے ہوتی ہے۔ پورا آدمی اگر معاشرے کے دباؤ یا کسی بھی وجہ سے اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا تو اسے اس کرب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسے یہ اجازت کسی طرح نہیں کہ وہ اپنی آسانی کے لیے اپنے آپ کوٹکڑوں میں بانٹ لے۔ کیوں کہ ٹکڑوں میں بانٹ لینے کے صرف ایک ہی معنی ہیں، اپنے وجود کے چند حصوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا۔ آنکھیں بند کر لینے سے وہ حصے اپنے اعمال سے تو باز نہیں رہتے، صرف آپ اپنے آپ کو یہ دھوکا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جھوٹی اخلاقیات یہیں سے شروع ہوتی ہے۔
رومانیت کاجھوٹ یہ ہے کہ وہ نچلے دھڑ کو ناپاک قراردے کر اوپر کے دھڑ کی تقدیس کے نغمے گاتی ہے اورعین اسی کی ناک کے نیچے نچلا دھڑ بڑے دھڑلے سے صرف شیطان کا آلۂ کار بن جاتا ہے۔ انسان کا اصلی گناہ یہی ہے۔ لیکن راشد ابھی اصلی اور نقلی گناہ کے فرق سے واقف نہیں۔ وہ ابھی رومانیت کے اس شیطانی فریب میں مبتلا ہیں کہ ان کا اپنے پورے وجود کو تسلیم کرنا گناہ ہے۔ بہر حال جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، انہیں اس فریب خوردگی کی پوری سزامل رہی ہے۔ نظم کا سب سے امید افزا پہلو یہ ہے کہ وہ اس فریب کو جس طرح محسوس کر رہے ہیں اسی طرح لکھ رہے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کوئی دھوکا دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نظم کو پڑھ کر امید بندھتی ہے کہ اب رومانی آدمی ضرور شکست کھائےگا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے صرف تقابلی دلچسپی کے لیے اختر شیرانی کی ایک نظم دیکھتے چلیے۔ یہ ایک تنہا نظم ہے جس میں رومانی اختر شیرانی کے بجائے اصلی اختر شیرانی ذرا سانس سی لیتا ہے۔ یعنی راشد کی طر ح اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نچلے دھڑ کو اوپر کے دھڑ سے ملاکر دیکھے۔
رات کا وقت ہے۔ لیلیٰ شب کے گیسو پریشان ہیں۔ ستاروں کی نگاہیں نشہ برسا رہی ہیں۔ واقعی بڑا سہانا وقت ہے۔ کیا اچھا ہو اگر اختر شیرانی ایک بار ہمت کرکے اپنے پورے وجود کو تسلیم کر لے۔ شاید اس کی اپنی طبیعت بھی اس پر مچل رہی ہے مگر اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے۔ کیا ہوگا، اختر شیرانی’’شہزادہ‘‘ کی بلندیوں سے اتر کر صرف’’آدمی‘‘ رہ جائےگا۔ جس میں نہ فرشتے کی پاکیزگی ہوتی ہے نہ روحوں جیسی معصومیت۔ جس کی بلندیوں کے ساتھ پستیاں لگی ہوئی ہیں اور لطافتوں کے ساتھ کثافتیں۔ اختر شیرانی اگر یہ آدمی بن گیا تو اسے شہزادی کی ضرورت نہیں رہےگی، نہ حور کی، نہ سلمیٰ کی۔ اسے اپنے ہی جیسی کسی’’معمولی‘‘ عورت کو قبول کرنا پڑےگا۔ اس لیے اختر شیرانی بھی ڈر رہا ہے،
چارسو چھا گئی خاموشی و ظلمت کی سپاہ
نور و آہنگ نے لی راہ فرار
نیند کی سیج سے جاگ اٹھاہے خوابیدہ گناہ
شیر خوں خوار ہو جیسے بیدار
ڈرو نہیں شاعر رومان، یہ شیر صرف بہروپیے شہزادوں کا خون پیا کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی طر ح پہچانتا ہے کہ آدمی کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اس لیے وہ آدمی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں لوٹنے لگتا ہے۔ ہمت کرو۔ شہزادے سے، کسری آدمی سے، ٹوٹی پھوٹی مضحکہ انگیز اور قابل نفرت مخلوق سے گزر کر آدمی بن جاؤ۔ آپ نے قصے کہانیوں میں پڑھایا سنا ہوگا کہ جب کبھی کوئی بلا اپنی محبوبہ یا محبوب کے پاس کسی آدمی کی موجودگی محسوس کرتی ہے تو’’مانس گند، مانس گند‘‘ کہتی دوڑٹی پھرتی ہے۔
سلمیٰ بھی ایک بلا ہے اور بلائیں ہزاروں روپ بدل سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ اپنے ’’شہزادے‘‘ کے پاس آدمی کے پہنچنے کی خبر سن کر کس طرح دوڑی دوڑی آئےگی۔ اس کا حلیہ بھی دیکھ رکھیے۔ معصوم اور مقدس صورت۔ گہرے غم ناک لہجے اور سوزناک آواز میں بولےگی۔ انداز تخاطب میں فرشتوں کی شان ہوگی۔ اس حلیے کو یاد رکھیے۔ یہ میں نے آپ کو شناخت بتا دی ہے جس سے آپ ہر بلاکو پہچان سکتے ہیں، چاہے اس کا کوئی بھی روپ ہو۔ انسانیت کے سارے جھوٹے مسیحاؤں کا روپ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے سلمیٰ بھی اختر شیرانی کی مسیحائی کے لیے آ رہی ہے تاکہ اسے ’’گناہ‘‘ سے بچائے،
یہ سماں دیکھ کے اک حور وہاں آتی ہے
مشک بو زلفوں کو لہرائے ہوئے
اور نظر اس ہوس آباد پہ دوڑاتی ہے
فرط تقدیس سے گھبرائے ہوئے
عالم یاس میں مبہوت سی رہ جاتی ہے
اشک غم آنکھوں میں چھلکائے ہوئے
چاند کی روشنی اک نشہ سا برساتی ہے
سینۂ صاف پہ لہرائے ہوئے
اچھا سینہ دکھاکر دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ بہ قول راشد’’حسرت اظہار شباب۔‘‘ آگے سنیے،
اک فرشتوں کے سے لہجے میں وہ کرتی ہے خطاب
آہ وہ لہجہ حزیں وغم ناک
کہ تم اے راہزن عصمت وآوارہ شباب
سرخوش و بے خود و مست و ناپاک
کیا لہجہ ہے؟ گویا بائبل کی آیات دہرائی جا رہی ہیں۔ خیر پوری نظم تو’’معصومیت‘‘ کے عنوان سے ’’صبح بہار‘‘ میں دیکھیے۔ ہمیں تو اختر شیرانی کے انجام سے دلچسپی ہے۔ نظم کا آخری بند دیکھیے،
آئےگا ایک دن آئےگا کہ شرماؤگے تم
اور میں ہاتھوں سے نکل جاؤں گی
عالم یاس میں میرے لیے گھبراؤگے تم
اور میں صورت بھی نہ دکھلاؤں گی
پچھلی بد ذوقیوں کو ذہن میں جب لاؤگے تم
شرم بن کر تمہیں شرماؤں گی
’’بدذوقی‘‘ کے الفاظ نے کیا مزہ دیا ہے۔ واقعی بن جانا’’شاعرانہ‘‘ خوش ذوقی کے خلاف ہے۔ آخری شعر ہے،
یاد کرکے مجھے پھر روؤگے پچھتاؤگے تم
میں مگر ہاتھ نہیں آؤں گی
میرا خیال ہے کہ اس آخری شعر کی دھمکی پر اختر شیرانی اسے نکاح کا پیغام دے دیتے تومزہ آ جاتا۔ مگر نکاح تو ہمارے پیغمبر رومان کی شریعت میں شعریت کا خون ہے۔ اس سے ’’بچوں کا فحش ترانہ‘‘ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اختر شیرانی پھر وہی ادھورے کا ادھورا رہ جاتا ہے۔۔۔ سلمیٰ کا شہزادہ! ن م راشد کی محبوبہ بھی کچھ سلمی سے ملتی جلتی ہے۔ البتہ راشد چوں کہ رومانیت کی دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس ’’حور‘‘ کے ’’تقدس‘‘ سے دبک کر اپنے مصنوعی خول میں چھپنے کے بجائے اس پر تنقید شروع کر دیتا ہے۔ اس تنقید کی تفصیل ’’حزن انسان‘‘ میں ملاحظہ کیجیے،
جسم اور روح میں آہنگ نہیں
لذت اندوز دل آویزئی موہوم ہے تو (’’لذت اندوزدلآویزی موہوم‘‘ کا ٹکڑا دیکھئے۔)
تجھ کو ہے حسرت اظہار شباب
اور اظہار سے معذور بھی ہے (وہی سینہ دکھانے والی بات۔ مگریہ ٹھنڈی گرمیاں ہیں۔)
جسم نیکی کے خیالات سے مفرور بھی ہے
اس قدر سادہ ومعصوم ہے تو
پھر بھی نیکی ہی کیے جاتی ہے
کہ دل و جسم کے آہنگ سے محروم ہے تو
اس کے بعد جسم کی عظمت کا بیان ہے اور بہت خوبصورت ہے،
جسم ہے روح کی عظمت کے لیے زینۂ نور
منبع کیف و سرور
نارساآج بھی ہے شوق پرستار جمال
اک زمستاں کی حسیں رات کا ہنگام تپاک
اس کی لذت سے آگاہ ہے کون
عشق ہے تیرے لیے نغمہ خام
کہ دل و جسم کے آہنگ سے محروم ہے تو
ہندوستان اگر اس وقت راشد کی اس نظم کو سمجھ لیتا اور رومانیت اس کے لیے عشق کا’’نغمۂ خام‘‘ بن جاتی تو شاید میں یہ مضمون لکھتا تو سہی مگر اس طرح نہیں۔ مگر خود بقول راشد،
آہ انسان کہ ہے وہموں کا پرستار ابھی
حسن بےچارے کو دھوکا دیے جاتا ہے
ذوق تقدیس پہ مجبور کیے جاتاہے
یہاں دلچسپی سے خالی نہ ہوگا اگر میں اس نظم پر حیات اللہ انصاری صاحب کی تنقید بھی آپ کو سناؤں۔ یہ تنقید ہی ۱۹۳۶ والی نسل کو دس سال کے اندر اندر لے ڈوبی۔ انصاری صاحب فرماتے ہیں،’’راشد صاحب کے گناہ و ثواب کے تخیل میں عیش پرستی اور ’خود غرضی‘ایک نظریے کے روپ میں آکر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نظریہ ’حزن انسان ‘میں آکر بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اس نظم کے اوپر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ افلاطونی عشق پر ایک طنز اور نظم پڑھو تو اس میں طنز اور ظرافت کی جھلک تک نہیں۔ (خوب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نظم کو بس بریکٹ ہی میں سمجھتے ہیں، اور یہ طنز کے ساتھ ظرافت اپنی طرف سے چپکادی؟) پھر طنز کیسے ہوگیا؟ بہت غور کرنے سے پتاچلتاہے کہ شاعر کے تحت الشعور میں یہ بات بطور اصول مسلمہ کے موجود ہے کہ انسان کوچاہیے کہ صرف اس اصول پر عمل پیراہو جس سے اپنے جسم کوراحت ملے۔ (تھوڑا سااور غور کرکے پتا چلائیے کہ تحت الشعور کے بجائے یہاں تو جو چیز ہے شعور میں ہے۔ تحت الشعور میں صرف رومانیوں کے رہتی ہے ) لیکن محبوبہ کی یہ حالت ہے،
جسم نیکی کے خیالات سے مفرور بھی ہے
پھر بھی نیکی ہی کیے جاتی ہے
محبوبہ کے اس رویے پر تیکھا ہوکر راشد فقرہ کستا ہے، کس قدر سادہ ومعصوم ہے تو! (چلیے طنزنہ سہی، فقرہ کسنے کا تو آپ نے بھی اعتراف کیا) اسی اصول کی بنا پر راشد اس نظم کو طنز کہتا ہے۔ یہ تن پرستی اصول کیسے بن گئی؟‘‘ (اجی صاحب یہ ’’تن پرستی‘‘ یا’’من پرستی‘‘ نہیں ہے۔ آدمی کواس طرح کسر بنانا تو آپ جیسے لوگوں کو مبارک ہو۔ یاں تو تن اور من کو ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ )
حیات اللہ انصاری کایہ طویل اقتباس میں نے صرف اس لیے نقل کیا ہے تاکہ آپ اس وقت کے ہندوستان کے ایک بہت بڑے طبقے کی نفسیاتی حالت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اختر شیرانی کی مسخ شدہ مخلوق ایک طرف اور حیات اللہ انصاری ٹائپ کے بقراط اور ان کی ذریات دوسری طرف۔ پھر جمال پرستوں، فطرت پرستوں، قوم پرستوں کی لاکھوں کروڑوں کسری شکلیں اس پر مستزاد۔ ان حالات میں راشد اپنا کام کر رہا تھا اور راشد کے ساتھ ہندوستان کا نیا نوجوان، پورا غیر کسری نوجوان، انسانی شکل کی ان غیرانسانی بلاؤں کے جنگل میں اپنا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔
مزے کی بات یہ ہے کہ آگے چل کر خود حضرت انصاری یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ شہوت حیوانی بقائے نسل کے لیے ضروری ہے اور اگر یہ جذبہ تن درست حالت میں نہ پایا جائے تو نسل انسانی اور افراد، دونوں کو نقصان پہنچتاہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب معلومات بس کتابیں رٹ رٹا کر ہی حاصل ہوئی ہیں، ورنہ یہ لکھتے کہ ہماری پوری قوم کی شہوت ایک مہلک مرض یعنی رومانیت (جنسی، سیاسی) میں مبتلا ہے، اورراشد اسی کے خلاف جدوجہد کرکے ان نفسیاتی الجھنوں کو شعور میں لاکر ان کا علاج کر رہا ہے جنہوں نے جنس کے بنیادی اور اہم جذبے کو نقصان پہنچا کر نسل انسانی اور افراد، ددنوں کو نقصان پہنچایا ہے۔
آخر میں اتنا اور عرض کروں کہ جناب انصاری! یہ شاعری ہے۔ یہ انسانوں کا علاج اس طرح نہیں کرتی جس طرح صحافت کرتی ہے۔ اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو نفسیاتی الجھنیں قوم کے یانسل انسانی کے اجتماعی لاشعور میں پروان چڑھ رہی ہوں، انہیں اپنے عمل سے شعور میں لے آئے۔ اچھا صاحب، اب آپ یہ تو دیکھ چکے کہ راشد کا’’میں‘‘ رومانیت کی دلدل سے ابھر کر نکل آنے کی کتنی جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ راشد اس جنگ میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ’’حزن انسان‘‘ کی محبوبہ اور’’مکافات‘‘ کے عاشق کو کہیں ملانا چاہیے تاکہ یہ جوڑا مکمل ہو جائے۔
ان دونوں کی حالت آپ جدا جدا دیکھ چکے ہیں۔ ادھر محبوبہ صاحبہ ہیں کہ اندر ہی اندر پسیجی جا رہی ہیں مگر اوپر سے سادہ و معصوم بنی ہوئی ہیں۔ ادھر عاشق صاحب ہیں کہ اندر سے گناہ کی حسرت میں سوکھے جا رہے ہیں مگر محبوبہ کا ہاتھ پکڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ہے اختر شیرانی اور سلمی کی ’’ملکوتی محبت‘‘ کا بھگتان جو ۱۹۳۶کے بعد آنے والی نسل کو بھگتنا پڑا۔ نچلا دھڑ جب ایک مرتبہ بھوت بن جائے تو بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ راشد اس بھوت کو کس طرح قابو میں لاتے ہیں۔
راشد صاحب اپنی نظم ’’میں اسے واقف الفت نہ کروں‘‘ میں جس سوال سے الجھ رہے تھے، گناہ اور محبت میں اس کا ایک دلچسپ حل ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یعنی محبوبہ سے اظہار محبت کر دیتے ہیں مگر جنس کا پہلو بچا جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ’’یہ ٹھیک ہے کہ عورت اور مرد میں جنسی تعلق ہوتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ تعلق گناہ ہے۔ (اگر بغیر نکاح کے یا نکاح کے بعد بھی جیسا کہ اختر شیرانی کا خیال ہے۔) مگر میں یہ گناہ بہت سی دوسری عورتوں کے ساتھ کر چکا ہوں اور تجربے سے یہ بات معلوم کر چکا ہوں کہ یہ بہت مہلک چیز ہے اور انسان کو بالکل تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے تم سے میری محبت جنسی تعلق کے بغیر ہوگی۔‘‘ یہ تو ہوا محبوبہ سے ان کے مکالمے کا خلاصہ۔ اب نظم ملاحظہ کیجیے،
گناہ کے تند و تیز شعلوں میں روح میری بھڑک رہی تھی
ہوس کی سنسان وادیوں میں مری جوانی بھٹک رہی تھی
مجھے خس ناتواں کے مانند ذوق عصیاں بہارہاتھا
گناہ کی موج فتنہ سامان اٹھااٹھا کر پٹک رہی تھی
شباب کے اولیں دنوں میں تباہ و افسردہ ہو چکے تھے
مرے گلستاں کے پھول جن سے فضائے طفلی مہک رہی تھی
غرض جوانی میں اہرمن کے طرب کا سامان بن گی امیں
گنہ کی آلائشوں میں لتھڑا ہوا اک انسان بن گیا میں
عاشق کو بھی اپنے مطلب کے لیے کیسے کیسے پلاٹ گڑھنے پڑتے ہیں، یہ تو آپ اپنے تجربے سے بھی جانتے ہوں گے۔ راشد کاپلاٹ بھی بالکل سیدھا ساداہے، اچھا صاحب اس کے بعد کیا ہوا،
ہوا ہوں بیدار کانپ کر اک مہیب خوابوں کے سلسلے سے
اور اب نمود سحر کی خاطر ستم کش انتظار ہوں میں
بہار تقدیس جاوداں کی مجھے پھر اک بار آرزو ہے
پھر ایک پاکیزہ زندگی کے لیے بہت بے قرار ہوں میں
مجھے محبت نے معصیت کے جہنموں سے بچا لیا ہے
مجھے جوانی کی تیرہ وتارپستیوں سے اٹھا لیا ہے
پہلے شعر میں جیسا کہ آپ نے تاڑ لیا ہوگا’’مہیب خوابوں‘‘ کا لفظ گناہوں کی تباہ کاری کی اس فرضی داستان کی اصل حقیقت فاش کر رہا ہے۔ بہر حال چلیے انگلی پکڑنے کی اس تکنیک کے سہارے اظہار محبت تو ہوا۔ اب انتظار اس بات کا کرنا ہے کہ یہ ڈرا ہوا جوڑا مصنوعی تقدس اور پاکیزگی کی اس پوٹ کو اٹھائے رہتا ہے یا اس میں اتنی جان ہے کہ اپنے پورے وجود کو تسلیم کر لے؟ ’’طلسم جاوداں‘‘ راشد کی خوب صورت ترین نظموں میں سے ایک ہے۔ یہاں تک کہ جناب انصاری بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں، گو سمجھ میں تو کا ہے کو آئی ہوگی۔ خیر نظم کا آغاز دیکھیے،
رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت
اب رہنے دے
اپنی آنکھوں کے طلسم جاوداں میں بہنے دے
تیری آنکھوں میں ہے وہ سحر عظیم
جو کئی صدیوں سے پیہم زندہ ہے
انتہائے وقت تک پائندہ ہے
پہلے مصرعے میں محبوبہ کو باتوں میں وقت کھونے سے منع کیا گیاہے۔ یاد رہے یہ وہی رومانی محبوبہ ہے جس سے آپ ’’حزن انسان‘‘ میں متعارف ہو چکے ہیں۔ رومانیت کی ابتدا جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک احساس کمتری ہے جو پہلے اپنی ایک تخیلی شخصیت پروان چڑھاتی ہے اور پھر اپنے محبوب کی (شہزادہ شہزادی) لیکن چوں کہ یہ صرف تخیلی شخصیتیں ہیں اس لیے ان دونوں کا رابطہ صرف ایک ہی چیز سے قائم ہوتا ہے۔ ’’باتوں‘‘ سے۔ اختر شیرانی کی رومانیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اور سلمی کے رومان کی انتہا یہ ہے کہ فطرت کی سجائی ہوئی سیج پر لیٹ کر نکہت و نور کی باتیں کریں۔ (یاد آیاکہ ماہنامہ’’ساقی‘‘ دہلی نے ایک مرتبہ بہت مقبول نمبر نکالا تھا’’باتیں نمبر۔‘‘ اس کے ساتھ اس زمانے کی سیکڑوں غزلیں یاد کیجیے جن کی ردیفیں باتیں، بات کرو، باتیں کریں۔ بات گئی وغیرہ ہیں۔ کہیں اس میں اس وقت کے ہندوستان کی اجتماعی ذہنیت کی کوئی رمز تو نہیں پوشیدہ ہے؟)
باتوں سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ نچلا دھڑ تو ہے ہی نہیں۔ انہیں تو سارا مزہ باتوں ہی میں لوٹ لینا ہے۔ ’’حزن انسان‘‘ کی محبوبہ کو’’گناہ اور محبت‘‘ کے بعد راشد صاحب راہ پر تولے آئے ہیں مگر اس بےچاری کو ابھی پرانی لت سے چھٹکارا نہیں ملا۔ باتوں کے بغیر اسے کچھ لطف ہی نہیں آتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان باتوں کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ مجھے شہزادی کہہ، میں تجھے شہزادہ کہوں۔ ورنہ اس کے بغیر دونوں صرف عورت اور مردرہ جائیں گے۔ رومانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اختر شیرانی اور سلمی کادل پسند کھیل یہی تھا۔ اب راشد کی باتیں سنیے،
دیکھتی ہے جب کبھی آنکھیں اٹھاکر تو مجھے
قافلے بن کر گزرتے ہیں نگہ کے سامنے
مصروہندو نجدوایراں کے اساطیر قدیم (لیجیے ساری دنیاکے شہزادوں شہزادیوں کو لپیٹ دیا ہے)
کوئی شاہنشاہ تاج و تخت لٹواتا ہوا
دشت و صحرامیں کوئی آوارہ شہزادہ کہیں
اور کوئی جاں باز کہساروں سے ٹکراتا ہوا (یہ رومانی جوڑوں کی باتوں کے دلچسپ ترین موضوعات ہیں )
اپنی محبوبہ کی خاطر جان سے جاتا ہوا
۔۔۔ (یہ نقطے بھی ایک مصرع ہیں )
قافلے بن کر گزر جاتے ہیں سب
قصہ ہائے مصر و ہندوستان و ایران و عرب
ایک کمال دیکھیے۔ چھوتھے مصرعے سے ’’اساطیر قدیم‘‘ کی تفصیلات بیان کرنی شروع کی ہیں مگر اس بد دلی سے جیسے کوئی طویل باتوں کی تلخیص کرتا ہے۔ چنانچہ آٹھویں مصرعے تک پہنچتے پہنچتے صرف نقطے باقی رہ جاتے ہیں۔ نقطوں کا مطلب ہے تفصیلات آپ خود بھرلیں۔ یعنی جس طرح بات مختصر کرنے کے لیے ہم لوگ ’’وغیرہ وغیرہ‘‘ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی اصرار، رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت۔ اس کے بعد راشد صاحب محبوبہ کو قربت کا اصل مفہوم سمجھاتے ہیں،
آج میں ہوں چند لمحوں کے لیے تیرے قریب
سارے انسانوں سے بڑھ کر خوش نصیب (پھر خوش کیاہے )
چند لمحوں کے لیے آزاد ہوں
تیرے دل سے اخذ نور ونغمہ کرنے کے لیے
زندگی کی لذتوں سے سینہ بھرنے کے لیے
اب نظم کا ایک بہت نازک ٹکڑا آتا ہے،
ایک دن جب تیرا پیکر خاک میں مل جائےگا
حیات اللہ انصاری صاحب کو اس پر اعتراض ہے کہ راشد ایذادہی کے مرض میں مبتلا ہے، اس لیے محبوبہ سے خلوت کرتے ہوئے بھی اس حرکت سے باز نہیں آتا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ’’ایک دن جب تیرا پیکر خاک میں مل جائےگا‘‘ کہنے کی ایذادہی کے سوا اور کوئی تک نہیں ہے۔ خیر ’تک بے تک ‘ کا حال تو وہی جانیں جو شاعری کوصرف ’تک بندی‘ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن اس مصرعے کو نکال دیجیے تو نظم میں ناقابل برداشت خلاپیدا ہو جائےگا۔ یاد رہے کہ اختر شیرانی صاحب سلمی کو یہ پٹی پڑھا چکے ہیں کہ ان دونوں کی محبت اور اس کے ذریعے سے وہ دونوں خود بھی ابدی ہیں۔ راشد کی محبوبہ چوں کہ رومانی رہ چکی ہے اس لیے وہ بھی اسی خبط میں مبتلا ہے۔ رومانیت جنسی ملاپ سے بچنے کے لیے اسی قسم کے ڈھکوسلے پیدا کرتی ہے، ورنہ عام انسانی جوڑے کی ابدیت کا کوئی امکان ہے تو صرف نسلی تسلسل کے ذریعے۔ اور نسلی تسلسل صرف باتوں سے قائم نہیں رہتا۔ اب اس مصرعے کے معنی’’ایذادہی‘‘ کے بجائے یہ نکلتے ہیں کہ راشد اسے ’’رومانی ابدیت‘‘ کے بے معنی چکر سے نکال کر حقیقی ابدیت کا راستہ دکھا رہے ہیں،
وقت کے اس مختصر لمحے کو دیکھ
تو اگر چاہے تو یہ بھی جاوداں ہو جائےگا
پھیل کر خود بے کراں ہو جائےگا
’’تو اگر چاہے‘‘ کا مطلب ہے، جنسی ملاپ پر محبوبہ کی رضامندی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ باتیں بند ہوں اور جذبے کو صرف خوب صورت لفظوں میں تحلیل کرنے کے بجائے اسے اپنے اندر خاموشی سے محسوس کیا جائے،
مطمئن باتوں سے ہو سکتا ہے کون
روح کی سنگین تاریکی کو دھو سکتا ہے کون
یہاں شاید محبوبہ باتوں سے رک جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر،
دیکھ اس جذبات کے نشے کو دیکھ
تیرے سینے میں بھی اک لرزش سی پیدا ہو گئی
زندگی کی لذتوں سے سینہ بھر لینے بھی دے
مجھ کو اپنی روح کی تکمیل کر لینے بھی دے
یہ نظم کا خاتمہ ہے۔ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ راشد کی محبوبہ اس وقت جنسی ملاپ پر رضامند ہوتی ہے یانہیں۔ لیکن ایک بات کا پتا ضرور چل جاتا ہے کہ اس کے جھوٹے رومانی خول میں چھپی ہوئی اصلی عورت پہلی بار ایک گہرا سانس بھر کر آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یہ دو مصرعے پھر پڑھیے،
دیکھ اس جذبات کے نشہ کو دیکھ
تیرے سینے میں بھی اک لرزش سی پیدا ہو گئی
مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے اور ابھی مجھے طویل سفر طے کرنا ہے۔ اس لیے میں ان نظموں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جہاں ’’مکافات‘‘ اور ’’حزن انسان‘‘ کے ہیرو ہیروئین جنسی ملاپ کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ مجھے اس وقت صرف اتنا ہی دکھانا تھا کہ راشد کی نظم نے پہلے تو رومانی انسان کی نفی کی اور اس کے نچلے دھڑ کو اوپر کے دھڑ سے جوڑ کر پورا آدمی بنا دیا۔ اور جب یہ آدمی مکمل ہو گیا تو اس نے اپنی محبوبہ کو بھی مکمل کر لیا (یہاں بات پر اور غور کیجیے۔ کیایہ عمل اپنی پوری تفصیلات اور نزاکتوں کے ساتھ اردو شاعری کی کسی اور مروجہ صنف میں دکھایا جا سکتا ہے؟ یہ ہے مواد اور ہیئت کا ناگزیر رشتہ) پھر بھی چوں کہ دونوں رومانی ذہنیت کا شکار رہ چکے ہیں، اس لیے رومانیت کا بھوت مختلف شکلوں میں ان کی تکمیل میں کھنڈت ڈالتا ہے۔ اور راشد نے ان کا بیان بھی بڑی ذہنی دیانت داری کے ساتھ کیا ہے۔ شاعری بہرحال کمیونسٹ پارٹی کا منشور تو نہیں ہوتی۔
راشد کایہ کارنا مہ کیا کم ہے کہ نئی نظم کی روایت میں پہلی بار اس نے ہمیں وہ پورا عمل دکھایا جس کے ذریعے ہم رومانیت اور کسری آدمی کے بھوتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ان معنوں میں راشد کی ’’ماورا‘‘ صرف نئی نظم ہی میں نہیں، پوری اردو شاعری (اگر اسے ایک مکمل تاریخی تسلسل کی روشنی میں دیکھا جائے) میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب تک اسے اہل مکتب کی غلطی اور خودراشد کی مرض کی حد تک بڑھی ہوئی جدیدیت پرستی اور اردو شاعری کی قدیم روایت سے ناقابل معافی اور ناقابل تلافی بےخبری کے باعث اردو شاعری کی قدیم روایت سے بغاوت کے طور پر سراہا گیا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس یہ ہے کہ ’’ماورا‘‘ میں اردو شاعری ایک بار پھر اسی قدیم روایت سے رشتہ جوڑ لیتی ہے، جس میں کسری آدمی کے بجائے پورا آدمی بولتا ہے۔
آخر میں ایک ہول ناک بات۔ ابھی میں نے ’’ماورا‘‘ کی چند نظموں کے ذریعے دکھایا ہے کہ ۱۹۳۶کے آس پاس کے زمانے میں کیسی شاعری اس سے پیدا ہوئی۔ بالآخر پوراآدمی بننے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہول ناک بات یہ ہے کہ اسی کتاب میں وہ عمل بھی دکھایا گیا ہے جس سے گزر کر دس سال کے اندر اندر یہ آدمی پھر ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے اور۱۹۶۱تک پہنچتے پہنچتے ہم سب اور ہم سب کے ساتھ راشد صاحب بھی خود فراموشی کی اس بھول بھلیاں میں گم ہو جاتے ہیں جو شاید غدر کے تاریک ترین دور میں بھی اتنی تاریک نہیں تھی۔ غدر کے بعد پورا آدمی ٹوٹ پھوٹ کر سیاسی، اخلاقی، اصلاحی، روما نی آدمی کی شکل میں زندہ رہا تھا۔ ۱۹۶۱میں یہ ساری شکلیں بھی موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں سیاست، اخلاق، اصلاح، رومان، کسی چیز سے بھی کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ صورت حال یقیناً پہلے سے زیادہ ہول ناک ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے آگے کیاہے کیوں کہ (نئی نسل مجھے معاف کرے) شاعری نے ہمیں راستہ دکھانا چھوڑ دیا ہے۔
یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر راشد صاحب کو کیا ہوا؟ میرے سامنے ایک اس سے بھی بڑا سوال ہے۔ آخر ہندوستان کی اس نئی نسل کیا ہوا جو راشد کی شاعری کے ساتھ ساتھ ۱۹۳۶ میں ابھری تھی، اور اس قوت کے ساتھ کہ سارے ہندوستان کی نگاہیں اس پر لگ گئی تھیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ۱۹۳۶ کی تحریک کو ٹیگور، پریم چند اور مولانا حسرت جیسے بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوئی تھی۔ سجاد ظہیر صاحب نے اپنی تصنیف ’’روشنائی‘‘ میں اس کا ساراک ریڈٹ ’’ترقی پسندوں‘‘ کو دیا ہے۔ چلیے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر تب ترقی پسندی کا مفہوم اتنا تنگ نہیں تھا جتنا محترمی (اسٹالن کے گھونسے کی شکل والے) علی سردارجعفری کے دور عروج میں ہوا۔ اس وقت تو ہر نیا لکھنے والا ترقی پسند تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے عسکری صاحب بھی جن کا نام تک قبلہ سجاد ظہیر نے اپنی تصنیف لطیف میں نہیں لیا ہے۔
اور آخر میں ایک اس سے بھی بڑاسوال۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ادیب اور اس کا قاری ہم شکل ہوتا ہے تو پھر یہ بھی سوچنا پڑےگا کہ راشد کاقاری کہاں گیا۔ راشد کااور میراجی کا اور منٹو کا اور عصمت کا۔ کیا رومانیت کی بلا سے بچنے کے بعد اسے کوئی اور بلا اچک لے گئی؟ افسوس کہ ان سوالوں کے بنے بنائے جواب ہمیں بازار میں نہیں ملتے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب مل جل کر ان پر غور کریں؟ لیکن ٹھہریے۔ ان سوالوں کے چکر میں پڑکر میں میراجی کو تو بھول ہی گیا۔
آیئے چند لمحے اردو کے اس بدنام شاعر کے ساتھ گزاریں جسے اس کے بہترین مداحوں نے بھی صرف میراسین کے اصلی یافرضی عاشق کی حیثیت سے یاد رکھا اور یہ بھول گئے کہ ہندوستان کی بےقرار حقیقت نگر اور سوگوار روح میراجی کی شاعری کے ذریعے کس کھوئی ہوئی ہم آہنگی کی تلاش میں ہے؟
میراجی کی شاعری کے بارے میں ایک اعتراف پہلے ہی کر لوں۔ ان سے اپنی ساری دلچسپی کے باوجود میں یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ انہیں میں نے پوری طرح سمجھ لیا ہے۔
ان کے بہت سے عجیب عجیب قصے، لطیفے اور واقعات مختلف ذرائع سے مجھ تک پہنچے ہیں جن کے متعلق میں ایک بات بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے مجھے ان پر کچھ حیرت ہوئی ہو لیکن گھن کبھی نہیں آئی۔ مرد مجرد کے مٹھولوں کا مزہ کچھ مرد مجرد ہی جانتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر تک بدن کے اس حصے کو ہاتھ نہیں لگایا جسے چھونے کے لیے میراجی پتلون ک ااستر غائب رکھتے تھے۔ لیکن یہ ہمت صرف میراجی کو ہوئی کہ وہ اسے چھپانے یا گندی بات سمجھ کر بھول جانے کے بجائے اپنے شخصی ارتقا کا ایک لازمی جزو سمجھ کر قبول کر لے۔
مجھے تسلیم ہے کہ یہ چیز یقیناً مریضانہ بن جاتی ہے اگر عمر کے ایک خاص حصے کے بعد بھی باقی رہے، تو اس کے لیے ہم میراجی کی نفسیاتی عمر ان کی شاعری سے متعین کریں گے۔ اگر واقعی شاعری میں میراجی کی عمر صرف اٹھارہ برس ہی رہ جاتی ہے تو ان کی قسمت۔ میری ان سے کوئی رشتے داری تو نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑےگا کہ اس فعل کے بارے میں ان کا ذہنی رویہ کیا ہے؟ مٹھولوں سے پورامزہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ بھول جائے کہ وہ یہ لذت ہاتھوں کے ذریعے حاصل کر رہا ہے۔ بھولنے کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوئی خیالی پیکر، کسی حسینہ کی تصویر، کسی دوشیزہ کے کپڑے، حسب توفیق واستطاعت کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جسے آپ عورت کانعم البدل سمجھ لیں۔ اور کیا اچھا ہو اگر آپ اس کا کوئی اچھا سا نام بھی رکھ لیں۔ چلیے سلمی ہی سہی اور فعل کے دوران اسے بار بار دہراتے رہیں۔ اس سے لطف دو گنا چوگنا ہو جاتا ہے۔
اب ہم میراجی کی شاعری میں یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس فعل سے کتنا لطف اٹھاتے ہیں؟ نیز یہ بھی کہ اس فعل کو شاعرانہ تجربے کا موضوع بناتے ہوئے وہ ذہنی طور پر بے خبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں یابا خبر؟ آپ کو یاد ہوگا، اختر شیرانی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے انہیں ’’آج کی رات‘‘ میں یہی فعل کرتے ہوئے پکڑ لیا تھاجب کہ وہ خود بالکل بے خبری کے عالم میں تھے، آج کی رات، اف او میرے خدا، آج کی رات اور اگران تمام سوالوں کے جواب میں ہماری ساری تفتیش کا نتیجہ یہ نکلے کہ میراجی نے شاعرانہ تجربے کا کھٹ راگ صرف اس لیے پالا تاکہ وہ تمام چیزیں جو آگے چل کر فرد کی نفسیاتی الجھنوں کا باعث بنتی ہیں اور اسے اندر سے توڑ کر ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہیں، شعور میں لائی جائیں تو ہم ان سے رشتے داری نہ ہونے کے باوجود انہیں اردو شاعری میں ان کا اصل مقام دینے سے گریز نہ کریں گے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کرہم یہ دیکھیں گے کہ میراجی کی شاعری کا آدمی کس حد تک پورا آدمی ہے۔
آیئے اب سب سے پہلے اس بدنام نظم کو دیکھیں جس کے ذریعے میراجی کی شاعری میں مریضانہ ذہنیت ڈھونڈی جاتی ہے۔ ’’لب جوئے بارے‘‘ کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ۱۹۴۱کی نظموں میں سے ایک ہے اور میراجی کا نظموں کا مجموعہ ۳۴۔ ۱۹۳۳کی نظموں سے شروع ہوتا ہے۔ گویا میراجی نے یہ نظم اپنی شخصیت اور شاعری کی پختگی کے دور میں لکھی۔ اس لیے اس پر جلد بازی میں کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ نظم کا موضوع جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، استمنا بالید ہے اور میراجی نے اس موضوع کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ شعوری طور پر پیش کیا ہے۔ یہ ایک واضح شاعرانہ تجربہ ہے، نہ کہ شاعر کی کسی ڈھکی چھپی خواہش کا ڈھکا چھپا اظہار۔ ڈھکی چھپی خواہش کا ڈھکا چھپا اظہار وہ ہوتا ہے جس میں اظہار کرنے والا خود اپنی حالت سے آگاہ نہ ہو، مثلاً کوئی اپنی گفتگو میں ہاتھ اس طرح ہلائے جیسے استمنا بالید کر رہا ہو یابات کرتے ہوئے بیچ بیچ میں خالص جنسی قسم کی سسکی بھرے۔
میراجی نے اس کے بالکل برعکس شعوری طور پر اسے اپنے شاعرانہ تجربے کا موضوع بنایا ہے۔ نظم کے ابتدائی بند میں میراجی ایک عورت کے پیشاب کرنے کا منظر دکھاتے ہیں۔ نظم کا’’میں‘‘ جو ضروری نہیں کہ خود شاعر ہی ہو، عورت کو ایک جھاڑی کے پیچھے سے پیشاب کے لیے بیٹھتے دیکھتا ہے۔ جھاڑی بالکل قریب ہے۔ وہ بہت آسانی سے پیشاب کرنے کا تمام عمل دیکھ سکتا ہے مگر اس میں ایک نفسیاتی جھجھک ہے اس لیے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اس اثنا میں عورت اٹھ کر چل دیتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس ’’میں‘‘ کا تلازمۂ خیال ہے۔ صرف اتنی سی جھجک کی بنا پر کہ اس نے اپنی ایک خواہش کو دبایا، اسے استمنا بالید کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس جھجک کو نمایاں کرنے کے لیے ایسے مصرعے نظم میں بار بار آتے ہیں،
یہ بصارت کو نہ تھی تاب کہ وہ دیکھ سکے
یا
نغمہ بیدار ہوا تھا جو ابھی، کان ترے
کیوں اسے سن نہ سکے، سننے سے مجبور رہے
نظم کاخاتمہ بھی بالکل صاف ہے، ہاتھ آلودہ ہے، نم دار ہے، دھندلی ہے نظر۔ شاعر اسے بیان کرتے ہوئے بالکل نہیں جھجکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے ذہن میں کوئی گندگی نہیں۔
تصوف کی طرح شاعری بھی پورے آدمی کی معراج ’’مکمل وصال‘‘ کو ٹھہراتی ہے۔ شنکر آچاریہ نے بھی یوگا کے معنی یہی بتائے ہیں۔ ’’مکمل ملاپ، نہ کم نہ زیادہ۔‘‘ چنانچہ یہ صرف پورے آدمی کی معراج ہی نہیں، اس کی پہچان بھی ہے۔ اب تصوف اور شنکر آچاریہ کو تو چھوڑ دیجیے اور شاعری کے ’’وصال‘‘ کی طرف آجائیے۔ مکمل وصال وہ ہے جو نفسیاتی الجھنوں کے بغیر ہواور جس میں دو بالکل مختلف وحدتیں مل کر ایک نئی وحدت میں گم ہو جائیں۔ یہ عمل فرد کو، وہ مرد ہو یا عورت، اس کی انفرادی حدود سے باہر لے جاتا ہے اوراس طرح وہ اپنے آپ کو کائناتی وحدت کے ایک جزو کے طور پر محسوس کر لیتا ہے۔ یعنی اس حقیقت کے ایک حصے کی حیثیت سے جو زمان ومکان سے ماورا ہے، جو خود حیات ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے۔ فردکے لیے یہ منزل بڑی کٹھن ہوتی ہے، کیوں کہ اسے اپنی انفرادیت سے باہر نکلنے میں اپنی ’’فنا‘‘ نظر آتی ہے۔ اس حقیقت کو صرف انفرادیت سے باہر نکلنے والاہی جانتا ہے کہ وہ فنا نہیں بقا ہے اور موت کا خوف صرف انفرادیت کے خاتمے کا خوف ہے۔ اب ہم میراجی کی نظموں کے ذریعے دیکھیں گے کہ ان کی شاعری کا آدمی اس معیار پر کہاں تک پورا اترتا ہے۔
’’لب جوئے بارے‘‘ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ میراجی کا اصل موضوع دراصل ایک نفسیاتی الجھن ہے جس کی سزا نظم کے ’’میں‘‘ کو استمنا بالیدکی صورت میں ملتی ہے۔ نفسیاتی الجھنیں میراجی کی نظموں کا خاص موضوع ہیں جنہیں وہ بڑی فنکاری سے ان کے آخری نتیجے تک لے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے قاری کی الجھنوں کو لاشعور سے شعور میں لاکر اس کے نفس کا تزکیہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا جی نفسیاتی الجھنوں کو صرف انفرادی معاملہ نہیں سمجھتے جیساکہ ترقی پسندوں کا خیال ہے بلکہ انہیں اپنے زمانے کے مخصوص معاشرے کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ ’’برقعے‘‘، ’’تن آسانی‘‘، ’’ایک تھی عورت‘‘، ’’تفاوت راہ‘‘، ’’رخصت‘‘، ’’دن کے روپ میں رات کہانی‘‘ اسی قسم کے مطالعے ہیں اور میراجی نے بڑی فنکاری سے ان کی تکمیل کے کٹھن مرحلوں کو طے کیا ہے۔
’’برقعے‘‘ میں ان کا موضوع’’لباس پرستی‘‘ ہے۔ لباس انسان کے لیے ضروری ہے لیکن جب آدمی لباس پر ضرورت سے زیادہ زور دینے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہے۔ میراجی نے اس نظم میں دکھایا ہے کہ لباس پرستی، اس چھپی ہوئی نفرت کو جنم دیتی ہے جو عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہونے دیتی اور نتیجہ ایک مستقل ہرجائی پن کی شکل میں نکلتا ہے۔ نظم کی اصلی خوبی یہ ہے کہ میراجی ساتھ ہی ساتھ آدمی کا اصلی معیار بھی دکھاتے جاتے ہیں،
پہلے پھیلی ہوئی دھرتی پہ کوئی چیز نہ تھی
صرف دو پیڑ کھڑے تھے۔ چپ چاپ (یہ آدم و حواہیں )
ان کی شاخوں پہ کوئی پتے نہ تھے (برہنہ تھے )
ان کو معلوم نہ تھا کیا ہے خزاں کیا ہے بہار
پیڑ نے پیڑ کو جب دیکھا تو پتے پھوٹے
وہی پتے۔ وہی بڑھتے ہوئے ہاتھوں کے نشان
شرم سے بڑھتے ہوئے، گوہر تاباں کو چھپاتے ہوئے، سہلاتے ہوئے
وقت بہتا گیا، جنت کا تصور بھی لڑھکتے ہوئے پتھر کی طرح
دور ہوتا گیا، دھندلاتا گیا
پتے بڑھتے ہی گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے
نت نئی شکل بدلتے ہوئے کروٹ لیتے
آج ملبوس کی صورت میں نظر آتے ہیں
اس کے بعد ’’لباس پرستی‘‘ کا نتیجہ دکھایا گیا ہے،
آج تو آنکھ کے دشمن ہیں تمام
آنکھ اب چھپ ہی کے بدلہ لےگی
جھلملاتے ہوئے پتے تو لرزتی ہوئی کرنوں کی طرح سایوں میں کھو جائیں گے اور بھڑکتے ہوئے شعلے بھی لپکتے ہوئے سوجائیں گے
دل میں سوئی ہوئی نفرت سگ آوارہ کے مانند اندھیرے میں پکار اٹھےگی
ہم نہ اب آپ کو سونے دیں گے (جنسی عمل سے فطری تسکین نہیں ہوگی، نیند نہیں آئےگی)
اور چپکے سے یہ آسودہ خیال آئےگا
آج تو بدلہ لیا ہم نے نگاہوں سے چھپے رہنے کا (گویا اب جو تسکین حاصل ہوگی وہ انتقام کے تصور سے ہوگی)
لیکن اب آنکھ بھی بدلہ لےگی
نئی صورت میں بدل جائےگی
’’تن آسانی‘‘ میں جنسی ناآسودگی کاسبب اس بات میں ڈھونڈا ہے کہ لوگ مکانوں کی ظاہری آرائش پر بہت زور دینے لگے ہیں، مثلاً گھر میں ٹائیلوں والا باتھ روم ضرور ہونا چاہیے۔ ’’کروٹیں‘‘ کا موضوع ایک ایسا شوہر ہے جو بیوی سے جنسی ملاپ کرتے ہوئے میٹھی میٹھی باتوں پر بہت زور دیتا ہے۔
نتیجہ
میٹھی باتوں کے نیچے جو پاتال ہے
اس کی گہرائی سے ایک زہر یلی ناگن ابھرآئےگی
رینگتے رینگتے اپنی پھنکار سے صاف کہہ دےگی، چاہو تو مانو اسے
لیکن اس کی ہر اک بات میں جھوٹ ہے یوں سمویا ہوا
جیسے بادل کے گھونگٹ میں کھویا ہوا
چاند کا روپ چھتی ہوئی تان کے بھیس میں
پھوٹ پڑتا ہے چشمے کی مانند لیکن بجھاتا نہیں پیاس کو
اور بھڑکا کے بے چین کرتا چلا جاتا ہے
چاند میراجی کی نظموں میں محبت کی علامت ہے یعنی جنسی جذبہ جب انفرادی شکل میں ہو۔ خود جنسی جذبے کی علامت رات ہے جو غیر شخصی ہے اور حیات کا مظہر ہے۔ رات کا سایہ جنس کا شخصی جذبہ اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کے مقابلے پر دن، فرد کی غیرجنسی زندگی کی علامت ہے۔ جب فرد، جنس کو غیرجنسی زندگی کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے تو رات کے سائے کے مقابلے پر دن کا سایہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے جنس سے حقیقی تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ اس سے صرف اپنی شخصیت کو سجا بناکر دکھانے کا کام لیتا ہے۔ محبوباؤں کا رجسٹر رکھنے والوں کاعشق اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ ’’دن کے روپ میں رات کی کہانی‘‘ میں یہی علامتیں استعمال کی گئی ہیں۔ نظم کا موضوع وہ لوگ ہیں جو اپنی محبتوں کو بھی اپنی ٹائی کی طرح شخصی دکھاوے کی چیز بنا لیتے ہیں۔ نظم کے کچھ حصے ملاحظہ کیجیے،
رات کے پھیلے اندھیرے میں کوئی سایہ نہیں
رات اک بات ہے صدیوں کی، کئی صدیوں کی
یاکسی پچھلے جنم کی ہوگی
رات کے پھیلے اندھیرے میں کوئی سایہ نہ تھا
رات کا پھیلا اندھیرا محتاج
اک بھکاری تھا اسی پہلی کرن کا جو لرزتی ہوئی آتی ہے جگا دیتی ہے
سوئے سایوں کو اٹھا دیتی ہے، بیداری میں
زیست کے ہلتے ہوئے، جھومتے آثار نظر آتے ہیں
زیست سے پہلے مگر بات کوئی اور ہی تھی
رات کے پھیلے اندھیرے میں کوئی سایہ نہ تھا
چاند کے آنے پہ سایے آئے
اب سایوں کی تفصیل بھی دیکھیے،
اس کے بکھرے ہوئے گیسو سائے
لاج کی میٹھی جھجک بھی سایہ
اور بھی سایے تھے ہلکے گہرے
کالی آنکھوں کی گھنیری پلکیں
اپنی آغوش میں سایوں کو لیے بیٹھی تھیں
اور ان سایوں میں محسوس ہوا کرتا تھا
دل کا غم، دل کی خلش، دل کی تمنا، ہر شے
اک سایہ ہے لرزتا سایہ جب یہ سایے اصلی ہوں تو ان کی ہی پہچان ہے۔ خاموشی (اس کے مقابلے پر رومانی حضرات کی باتیں یاد کیجیے۔)
رات کے سائے ہی خاموش رہا کرتے ہیں
دن کے سایے تو کہا کرتے ہیں
بیتی لذت کی کہانی سب سے
نتیجہ ازل اور ابد کے اس راستے پر، جو آدمی کی گزرگاہ ہے، نئے نئے سایے پیدا ہو گئے ہیں۔ انہیں بھی دیکھ لیجیے،
راہ میں آتی ہوئی ہر مورت
اک سایہ ہے۔ چڑیل
دیکھتے ہی جسے میں کانپ اٹھا کرتا ہوں
آنکھوں میں خون اتر آتا ہے
دل دھڑکتا ہی چلا جاتا ہے
اور میں دیکھتا ہوں
سایے ملتے ہوئے، گھلتے ہوئے، کچھ بھوت سے بن جاتے ہیں
ہنہناتے ہوئے ہنستے ہیں، پکار اٹھتے ہیں
دل میں کیا دھیان یہی ہے اب بھی
سایہ خاموش رہا کرتا ہے؟
دیکھ ہم بولتے ہیں، بولتے سایے ہیں تمام
ہم سے بچ کر تو کہاں جائےگا
اور میں کانپ اٹھا کرتا ہوں
اسی موضوع پر ایک نئے غزل گو کا شعر سنیے،
عشق فسانہ تھاجب تک اپنے بھی بہت افسانے تھے
عشق صداقت بنتے بنتے کتنا کم احوال ہوا
اطہر نفیس
اسی طرح کی دوسری نظموں میں جنگل اور باغ کی علامتیں استعمال کی گئی ہیں۔ سمندر کی علامت بھی میراجی کو بہت محبوب ہے۔ ایک بہت خوب صورت نظم ’’دھوکا‘‘ میں یہی علامت برتی گئی ہے۔ سمندر غیرشخصی جنسی جذبہ ہے۔ کنواں وہ جنسی جذبہ ہے، جو صرف شخصی ہوکر رہ جائے اور جس میں انفرادیت کی حدود سے گزر جانے کی صلاحیت نہ ہو۔ نظم کا موضوع ایک ایسی عورت ہے جو خود کو کنواں سمجھتی ہے مگر صحیح تجربے کے بعد سمندر بن جاتی ہے۔ اسی طرح ’’ایک تھی عورت‘‘ میں میراجی نے سمندر کی دو قسمیں کر دی ہیں،
یہ جی چاہتا ہے کہ ہم ایسے ساگر کی لہروں پہ ایسی ہوا سے بہائیں
وہ کشتی جو بہتی نہیں ہے، مسافر کو لیکن بہاتی چلی جاتی ہے اور
پلٹ کر نہیں آتی ہے، ایک گہرے سکوں سے ملاتی چلی جاتی ہے
(وہی انفرادیت کو توڑ کر ایک نئی وحدت میں گم ہو جانے کا عمل۔) یہ جنسی جذبے کا صحیح ترین عمل ہے۔ اس کے مقابلے پر دوسرا ساگر دیکھیے،
وہ ساگر جو بہتے مسافر کو آگے بہاتا نہیں ہے، جھکولے دیے
جاتا ہے، بس جھکولے دیے جاتا ہے
نتیجہ آدمی ایسی عورت سے جنسی ملاپ کے بعد خود جنسی جذبے ہی سے بیزاری محسوس کرنے لگتا ہے اور پھر جی ہی جی میں مسافر یہ کہتا ہے، اپنی کہانی نئی تو نہیں تھی،
پرانی کہانی میں کیا لطف آئے
ہمیں آج کس نے کہا تھا۔ پرانی کہانی سناؤ
آپ نے دیکھ لیا میراجی کس طرح اپنی شاعری میں کسری انسان کی شکلیں دکھاتے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے پر پورے آدمی کا پیمانہ رکھ کر بتاتے جاتے ہیں کہ جب تک وہ اس معیار پر نہیں آئےگا، ہنہناتی ہوئی ہنسی والے بھوت کاہم شکل رہےگا اور عورتیں بھی مایوس نہ ہوں، ان کے لیے چڑیلوں اور زہریلی ناگنوں کی شکلیں محفوظ ہیں۔ اب آخر میں میراجی کی وہ نظم دیکھ لیجیے جسے انہوں نے اپنے مجموعے کی پہلی نظم بنایا۔ ’’چل چلاؤ۔‘‘
نظم کا موضوع محبت، زندگی، ازل اور ابد پر محیط ہے اور میراجی اس نظم میں یہ بتاتے ہیں کہ جنسی جذبہ بھی زندگی کی طرح شخصی چیز نہیں ہے۔ محبت اگر سچی محبت ہے اور خود پرستی کی کوئی پر فریب شکل نہیں ہے تو وہ بھی گزرتے ہوئے لمحے کی طرح آنی جانی چیز ہے۔ محبت، آدمی، زندگی، سب اسی طرح رواں دواں ہیں۔ مسافروں کی طرح۔ یہ کائنات کا نظام ہے اور پورا آدمی وہ ہے جو کائنات کے نظام سے ہم آہنگ ہوتا ہے اور شخصی ضد، خود پرستی یا خودنمائی کی بنا پر اس سے انحراف نہیں کرتا۔ وہ دکھ بھوگتا ہے، سختیاں سہتا ہے، مگر زندگی کا، کائنات کا اور اس طرح اپنے خدا کا اثبات کرتا ہے،
بس دیکھا اور پھر بھول گئے
جب حسن نگاہوں میں آیا
من ساگر میں طوفان اٹھا
طوفان کو چنچل دیکھ ڈری، آکاش کی گنگا دودھ بھری
اور چاند چھپا، تارے سوئے، طوفان مٹا، ہر بات گئی
دل بھول گیا پہلی پوجا، من مندر کی مورت ٹوٹی
دن لایا باتیں انجانی، پھردن بھی نیا اور رات نئی
پیتم بھی نیا، پریمی بھی نیا، سکھ سیج نیا، ہر بات نئی
اک پل کو آئی نگاہوں میں جھلمل کرتی پہلی سندرتا
اور پھر بھول گئے
لیکن یہ ہوس اور ہرجائی پن نہیں ہے۔ وہ تو مسخ فطرت آدمی کی جنسی شکلیں ہیں،
جوبات ہو دل کی آنکھوں کی تم اس کو ہوس کیوں کہتے ہو
جتنی بھی جہاں ہو جلوہ گری اس سے دل کو گرمانے دو
جب تک ہے زمیں
جب تک ہے زماں
یہ حسن و نمائش جاری ہے
اس ایک جھلک کو چھچھلتی نظر سے دیکھ کے جی بھر لینے دو
یہ ’’جی بھرلینے دو‘‘ کا ٹکڑا کتنا حسرت ناک ہے اور اگر آپ اوپر کے قافیے کی گونج کے سبب’’جی بھر لانے دو‘‘ پڑھ جائیں تو یہ وہی چیز ہے جسے حافظ نے ’’رقت‘‘ کہا (کہ بے رقت نہ دیدم ہیچ شے را) نظم کا خاموش آہنگ اور ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی آنچ بھی دیکھتے چلیے،
ہر منظر، ہر انساں کی دیا، اور میٹھا جادو عورت کا
اک پل کو ہمارے بس میں ہے، پل بیتاسب مٹ جائےگا
اس ایک جھلک کو چھچھلتی نظر سے دیکھ کے جی بھر لینے دو
تم اس کو ہوس کیوں کہتے ہو
کیا داد جو اک لمحے کی ہو، وہ داد نہیں کہلائےگی
ہے چاند فلک پر اک لمحہ
اور اک لمحہ یہ ستارے ہیں
اور عمر کا عرصہ بھی سوچو، اک لمحہ ہے
یہاں میں ایک بات آخر میں کہہ دوں۔ یہ شاعری جیسی بھی ہے اور آپ اس کو جو مقام بھی دیں، لیکن ایک ایسی شاعری سے جس کا مقابلہ چند ایسے مسائل سے تھا جس سے اردو زبان کی شاعری کو اب تک کسی دور میں بھی سابقہ نہیں پڑا تھا، ان مسائل کو ان کی پوری شکل میں نمایاں کرنے اور اپنے مقدور بھر انہیں ہندوستان کے شعور میں رچانے بسانے کے لیے اس شاعری نے ایک ہیئت اخیتار کی۔ میراجی کی شاعری کو آپ اس ہیئت کا آخری شاہ کار قرار دیں یانہ دیں، اس کی اولیت ان سے نہیں چھین سکتے۔
شاعرانہ روایتوں کو پیدا ہونے اور پروان چڑھنے میں تو صدیاں لگتی ہیں۔ پتا نہیں سوپچاس سال کی مستقل کوششوں کے بعد اس روایت میں کس رتبے کی شاعری ہو، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، یہ روایت جب تک قائم ہے اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر بھی وہ میراجی کی مرہون منت رہے گی۔ جس نے بہ یک وقت کسری آدمی اور پورے آدمی کو ایک دوسرے کے تقابل میں رکھ کر دیکھا اور کسری کی پیدائش کی مختلف صورتوں پر غور کیا۔
ایلیٹ نے کہیں لکھا ہے کہ شاعری میں ہمیشہ دکھ بھوگنے والا انسان اور ان کا مشاہدہ کرنے والا انسان الگ الگ ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں جتنے الگ الگ ہوں گے اتنی ہی بڑی شاعری پیدا ہوگی۔ میں اسے اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کروں تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ شاعر میں دو قوتیں ہونی چاہییں۔ ایک تو وہ قوت جسے میں نے پورا آدمی کہا اور جو ایک معیار ہے۔ دوسری قوت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے ’’ٹھوس اور محدود‘‘ آدمی کی شکل اختیار کر سکے۔ ورنہ وہ انہیں پورے آدمی کے معیار پر ٹھیک طرح سے نہیں پرکھ سکےگا۔ ’’تجربہ‘‘ انہیں معنوں میں شاعر کے لیے لازمی شرط ہے۔
اب اس اصول کو میراجی پر اور ان کے مخصوص زمانے پر منطبق کیا جائے تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آجاتاہے کہ اپنے زمانے کے مخصوص آدمی کی تمام شکلیں دیکھنے اور پھر انہیں اپنے پورے آدمی کے معیار پر پرکھنے کی جیسی صلاحیت میراجی میں تھی، ان کے زمانے کے کسی شاعر میں نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں میراجی وہ تنہا شاعر تھاجس کی ذات میں اس زمانے کی مخصوص روح اس کھوئی ہوئی ہم آہنگی کو تلاش کر رہی تھی جسے ہم نے ۱۸۵۷ کے ہنگامے میں کہیں گم کر دیا اور جسے ہم اب تک نہیں پا سکے ہیں بلکہ شاید اس کی تلاش بھی بھول بیٹھے ہیں۔
کاش میراجی کی نظم ’’اونچامکان‘‘ اس وقت ہماری سمجھ میں آ جاتی جب میراجی زندہ تھا اور اتنا مایوس نہیں ہوا تھا کہ شارع عام پر کھڑے ہو کر استمنا بالید کرنے کی حسرت کرے۔ اچھا اب ہمیں نہایت ادب کے ساتھ میراجی سے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ ابھی ہمیں ہنہناتی ہوئی ہنسی والے بھوتوں کے مہیب جنگل میں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ لیکن شاید’’روشنیوں کے شہر‘‘ والے فیض احمد فیض اس بات کا برا مان جائیں۔ اس لیے چلیے پہلے ان کی روشنیوں ہی کو دیکھ لیں۔
فیض صاحب عصر حاضر کے پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ تنہا ایک ایسے خوش نصیب شاعر ہیں جن سے پرانی نسل والے اثر لکھنوی بھی خوش ہیں اور بالکل نئی نسل والے ساقی فاروقی بھی۔ اور بیچ کی نئی نسل تو انہیں کا ایک پرتو ہے۔ اختر الایمان، ساحر اس نسل کے وقیع ترین نام ہیں اور فیض سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اور تو اور جناب مخدوم محی الدین بھی سینگیں کٹاکے بچھڑوں میں شامل ہو گئے اور اپنی ’’کفن سے منھ کو نکالے ڈرا رہا ہے قمر‘‘ والی شاعری چھوڑ کر سیدھا سادا فیض کا چربہ اتارنے لگے۔ اور چربہ بھی، افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ نہایت پھیکا۔ اس کے علاوہ روزناموں، ماہ ناموں اور سال ناموں میں چھپنے والی لاتعداد مخلوق فیض کی ذریات میں ہے اور انہی کے لب ولہجہ میں انہی جیسی ترکیبوں اور ذہنی تصویروں کے ساتھ مستقل دار پر چڑھنے کے درپے ہے۔
اب کون انہیں سمجھائے کہ فیض کے ساتھ ترقی پسندی نہیں ہے اور بھی پچیس چیزیں ہیں۔ آدمی جب فیض جیسی زندگی بسر کرے تب فیض جیسی شاعری کرے ورنہ لب و لہجہ میں یہ کچھ سوئی سوئی سی غنائیت کہاں سے آئےگی اور آئےگی تو باقی کہاں سے رہےگی جو ’’انقلاب‘‘ کو بھی ایک ایسی خواب آگیں لذت میں لپیٹ دیتی ہے جو صرف خلوت کی چیز ہے۔ فیض صاحب کی شاعری میں ایک کمال یہ دیکھا کہ سرمایہ داروں کی کوٹھیوں پر ہل چلانے کے خواب دیکھنے والے انقلابی بھی جھومیں اور کوٹھیوں کے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر انقلابیوں کو غدار کہنے والے سرمایہ دار بھی جھومیں۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ جانے فیض صاحب کی شاعری میں ایسا کیاجادو ہے کہ ہر ایک کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔
یہ سوال میرے لیے اور اہم ہو جاتا ہے جب میں ’’نقش فریادی‘‘ کے دیباچۂ طبع اول میں فیض صاحب کے یہ الفاظ پڑھتا ہوں،’’ہم سے بیش تر‘‘ کی شاعری کسی داخلی یا خارجی محرک کی دست نگر رہتی ہے اور اگر ان محرکات کی شدت میں کمی ہو جائے یاان کے اظہار کے لیے کوئی سہل راستہ پیش نظر نہ ہو تو یاتو تجربات کو مسخ کرنا پڑتا ہے یاطریق اظہار کو۔ ذوق اور مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ ایسی صورت حالات پیدا ہونے سے پہلے شاعر کو جو کچھ کہنا ہو کہہ چکے۔ اہل محفل کا شکریہ ادا کرے اور اجازت چاہے۔‘‘
تفصیل اس اجازت چاہنے کی یہ ہے کہ فیض صاحب محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے پاس کہنے کو اب کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ ’’آج سے کچھ برس پہلے ایک معین جذبے کے زیر اثر اشعار خود بہ خودوارد ہوتے تھے لیکن اب مضامین کے لیے تجسس کرنا پڑتا ہے۔‘‘ یہ خود انہی کے الفاظ ہیں۔ ہماری خوش قسمتی سے فیض صاحب نے اسی کیفیت کاصحیح تجزیہ بھی خود ہی کر دیا ہے،’’نوجوانوں کے تجربات کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتیں۔ ہر تجربہ زندگی کے بقیہ نظام سے الگ کیا جا سکتا ہے اور کیمیاوی مرکب کی طرح اس کی ہر ہئیت مطالعہ کی جا سکتی ہے۔‘‘
فیض صاحب محسوس کر رہے تھے کہ ان کی نوجوانی کے تجربات اور ان کی یادیں اب پہلے جیسی نہیں رہیں۔ ان کا ذہن اب پہلے سے زیادہ پختہ ہو چکا ہے اور اس میں زندگی کے کچھ نئے تجربات نے اپنے لیے جگہ بنالی ہے۔ ہر ایمان دار شاعر نوجوانی کی شاعری کے اولین تجربے کے بعد کچھ ایساہی محسوس کرتا ہے۔ ادھیڑ آدمی کی شاعری بھی ادھیڑ ہونی چاہیے۔ اس وقت بقول ایلیٹ، شاعر کے سامنے صرف تین راستے ہوتے ہیں۔ یاتو شاعری ایک سرے سے ترک کر دے یا پھر پرانے تجربات ہی کو زبان و بیان کی زیادہ پختگی کے ساتھ بیان کرنے لگے، یعنی استاد بن جائے اور آخری راستہ سیدھے سچے آدمی اور فنکار کا ہے۔ وہ یہ کہ اپنے تجربات کو قبول کرلے اور ان کے لیے کوئی موزوں پیرایۂ بیان اختیار کر لے۔ یہ تیسرا راستہ سب سے مشکل ہے مگر افسوس کہ شاعری کرنی ہے تو اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ فیض صاحب کا ارادہ پہلا راستہ اختیار کرنے کا تھا۔ وہ شاعری ترک کر دینا چاہتے تھے۔ وہ انہیں کی زبانی سنیے،
’’یہ تمام عمل (یعنی تجربات کے لیے نیا پیرایہ ٔ اظہار تلاش کرنا) مشکل بھی دکھائی دیتا ہے اور بےکار بھی۔ اول تو تجربات ایسے خلط ملط ہو گئے ہیں کہ انہیں علاحدہ علاحدہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا مشکل ہے۔ پھر ان کی پیچیدگی کو دیانت داری سے ادا کرنے کے لیے کوئی تسلی بخش پیرایۂ بیان نہیں ملتا۔‘‘ بہر حال فیض صاحب شاعری تر ک کرتے یا نہ کرتے، ان کا ارادہ استاد بننے کا بالکل نہیں تھا لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیض صاحب نے شاعری ترک نہیں کی اور ان کی شاعری کے میرے جیسے معمولی طالب علم کو بھی معلوم ہے کہ شاعری ترک نہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا نیا پیرایۂ اظہار بھی نہیں نکالا جس میں نوجوانی کے تجربات کے بعد والے تجربات اپنی کوئی نمایاں حیثیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ کیا فیض صاحب استاد بن گئے؟ میرا جواب انکار میں ہے۔ فیض صاحب کا کام استادی سے بہت بڑھا ہوا ہے۔
قبل اس کے کہ ہم اس کام کی تفصیلات میں جائیں، پہلے یہ بھی دیکھ لیجیے کہ فیض صاحب نے شاعری ترک کیوں نہیں کی۔ ’’نقش فریادی‘‘ کے دیباچۂ ثانی میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے،’’اس مجموعے کا پہلا ایڈیشن خلاف توقع بہت جلد ختم ہو گیا۔ ممنون ہوں۔ پبلشر کا کہنا ہے کہ دوسرے ایڈیشن کے تقاضے موصول ہو رہے ہیں۔‘‘ فیض صاحب چاہتے تھے کہ دوسرے ایڈیشن کو اس وقت تک روکے رکھیں جب تک ایڈیشن میں کافی قطع و برید کی گنجائش نکل سکے۔ ابھی توجہ واقعی شاعری کی طرف تھی۔ لیکن بھلا ہو پبلشر کا کہ اس نے انہیں یہ بتا دیا کہ ’’یہ تعویق تجارتی مفاد کے منافی ہے۔‘‘
مجبوراً فیض صاحب کو چار پانچ نظمیں حذف کر کے اور اتنی ہی نئی نظمیں بڑھاکر اجازت دینی پڑی۔ میں یہاں اس گھٹیاپن کا ثبوت نہیں دوں گا کہ تجارتی مفاد کا ذکر کروں۔ اس لیے صرف اتنا کہوں گا کہ مقبولیت شاعر کی آخری کمزوری ہے۔ ’’نقش فریادی‘‘ کی طبع اول سے فیض صاحب کو معلوم ہو گیا کہ شاعری صرف شاعر کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اس میں ایک تو پبلشر شامل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جن سے پبلشر کو اس کے کام کی قیمت ملتی ہے۔ دنیا کا تمام ہلکا پھلکا مقبول ادب اسی فارمولے سے پیدا ہوتا ہے،
پبلشر+خریدنے والے
لکھنے والا
اس جمع تقسیم میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ لکھنے والا غائب ہو جاتا ہے اور مقبول ادب باقی رہ جاتا ہے۔ ایک جذباتی ملغوبہ جو پڑھنے والے کو ایک جھوٹی تسکین یا خواب آور لذت دے سکے۔ یہی فارمولا فلموں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مقبول عام فلمی پرچوں میں بھی۔ اس کے بعد فیض صاحب کو اپنے پبلشر کی مدد سے صرف اتنا ہی کرنا پڑا کہ اپنے پڑھنے والوں کی ذہنیت، عمر اور نفسیاتی کیفیت کے بارے میں مستند معلومات حاصل کر لیں اور آگے اللہ مالک ہے۔ سو اللہ نے بھی اپنے مالک ہونے کی لاج رکھی اور مقبولیت فیض صاحب پر ساون کی جھڑیوں کی طرح چھماچھم برسی۔ مگر وہ زندہ، سچا، حساس شاعر کہاں ہے جس کی زندگی نے اسے کچھ نئے تجربات دیے تھے اور ایسے تجربات کہ ان کے اظہار کی کٹھن راہوں سے گزرنے سے گھبراکر وہ شاعری ترک کر دینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ پتا نہیں فیض صاحب اپنے آپ سے کبھی یہ سوال پوچھتے بھی ہیں یا نہیں۔
خیر، میں تو ان کا ایک معمولی قاری ہوں اور ان کی کتابیں خرید کر پڑھتا ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میں صرف یہ دیکھوں گا کہ ان کی شاعری صرف انہیں لوگوں کے کام کی ہے جنہیں ابھی میٹھا برس لگا ہے یاجو اٹھارہ برس کی عمر سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ یا مجھ جیسے ادھیڑ آدمی کے لیے بھی ان کے کلام میں کوئی گنجائش ہے؟ دوسرے لفظوں میں ان کے دیے ہوئے جذباتی ملغوبے کا تجزیہ کروں گا۔
اس سے پہلے میں ہندوستان کی ۱۹۳۶ کی نسل کا ذہنی تجزیہ کرتے ہوئے اپنے مقدور بھر دکھا چکا ہوں کہ اس پر اختر شیرانی کی رومانیت کاغلبہ تھا۔ رومانیت کے اجزائے ترکیبی بھی آپ دیکھ چکے۔ یہاں اس کے ایک عنصر کو خاص طور پر نگاہ میں رکھیے، ’’خودپرستی‘‘ کو۔ ’’خودپرستی‘‘ ہی سے لڑکی شہزادی بنتی ہے اور لڑکا شہزادہ۔ اور شہزادہ شہزادی کی محبت کا مقصد ایک دوسرے کی تکمیل نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنی تکمیل۔ دونوں قالینوں اور صوفوں کی طرح اپنے محبوب کو بھی ڈرائنگ روم میں سجانا چاہتے ہیں۔ تشریح کے لیے خود فیض کا شعر حاضر ہے،
اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں
ورنہ تجھ سے مجھ کو پیار نہیں
مجھے یاد ہے، میں پہلی مرتبہ یہ شعر پڑھ کر اچھل پڑا تھا۔ اعتراف کیوں نہ کرلوں کہ اس وقت ہم بھی بڑے پکے رومانی ہوتے تھے۔ اس لیے جب ’’نقش فریادی‘‘ چھپی تو مارے اشتیاق کے میرٹھ سے دلی دوڑ پڑے۔ مادام سمون دبوار کہتی ہیں کہ اٹھارہ برس کی عمر تک یہ معاف ہے کہ عمر کا تقاٖضہ ہوتا ہے۔ البتہ اس کے بعد ہر رومانی کو سیدھ سبھاؤ سے آدمی بن جانا چاہیے۔ کیوں کہ اس کے آگے کسری آدمی کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ ۱۹۳۶ میں فیض صاحب کی عمر پچیس سال ضرور رہی ہوگی۔ تب وہ ہم جیسے لونڈوں کے لیے شاعری کر رہے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ ۵۲، ۵۰ سال کی عمر میں بھی وہ ہمیں لونڈا سمجھتے رہیں گے۔ لیکن جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، انہوں نے یہ دریافت کر لیا تھا کہ رومانی نظموں میں جو کیفیت بیان کی جاتی ہے وہ خود بقول ان کے ’’اپنی سطحیت کے باوجود عالم گیر ہے۔‘‘ اس عالم گیریت کو ان کا پبلشر اور وہ خود کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح یہ شاعری اپنی ابتداہی سے عالم گیر سطحیت کی ترجمانی کا اہم کام اپنے ذمے لے لیتی ہے۔
رومانی خود پرستی اس عالم گیر سطحیت کاصرف ایک عنصر ہے۔ لڑکی اپنے آپ کو مرکز دوعالم سمجھتی ہے، لڑکا اپنے آپ کو۔ اور اس طرح محبت کا وہ کھیل شروع ہوتا ہے جسے آپ اختر شیرانی کی شاعری میں تفصیل سے دیکھ چکے۔ راشد نے ہمیں بتایا کہ اس کھیل میں بڑے مزے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں نچلے دھڑ کی دھما چوکڑی سے پورا کھیل ہی بگڑ جاتا ہے۔ میراجی اس سے بھی آگے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر آدمی نچلے دھڑ کی دھماچوکڑی کو شعور میں لاکر قابو میں نہ کرے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آدمی ہنہناتی ہوئی ہنسی والا بھوت بن جاتا ہے۔ اب ان سب باتوں کو دھیان میں رکھیے اور فیض صاحب کے آدمی کو فتوحات دیکھتے چلیے۔
اس آدمی کی سب سے بڑی خوبی اس کی استقامت ہے، یعنی یہ کسی طرح بھی رومانیت کا دامن نہیں چھوڑتا۔ محبوبہ صاف صریحاً جنسی تجربہ کے لیے رقیب کے ساتھ جاتی ہے تو یہ اس کے کرب کو بھی اپنی رومانی خودپرستی کے سر پر ایک رنگین پر کی طرح سجا لیتا ہے۔ فراق صاحب نے خدا جانے کس طرح اس گھناؤنے عمل کو اتنا سراہا تھا کہ کالی داس کو شرما دیا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارے پیرومرشد سے غزل کیوں نہیں ہو رہی ہے۔
لیکن فیض صاحب کے رومانی آدمی نے رقابت کو برداشت کرنے کے چکر میں ایک بڑے کام کی بات سیکھ لی۔ دردمندوں کی، غریبوں کی حمایت۔ محبوبہ صاحبہ نے عاشق کی یہ انسان پرستی دیکھی ہوگی تو خوشی سے پھولی نہ سمائی ہوں گی، کہ ایسا عاشق تو سلمیٰ کو بھی نہیں ملا۔ سلمی غریب کو تو اپنی خودپرستی کی قیمت یہ ادا کرنی پڑتی تھی کہ وہ کبھی جنسی تجربے سے آشنا ہی نہ ہو اور یہاں تو دونوں ہی میٹھے ہیں۔ رومانی محبت شاعر صاحب کے ساتھ، باقی دوسرے دھندے رقیب کے ساتھ۔ لیکن محترمہ اس کا نتیجہ آگے آتا ہے۔ آپ اپنی خودپرستی کے لیے اپنے عاشق کو پھول کی طرح بالوں میں سجاناچاہتی ہیں تو عاشق بھی آپ سے کم نہیں۔ اس نے بھی بڑی دور کی سوچی ہے۔
مزہ اس وقت آتا ہے جب فیض صاحب کی شاعری کا’’میں‘‘ محبوبہ کو یہ مژدہ سناتا ہے کہ وہ دردمندوں اور غریبوں کی حمایت کے کام میں بہت مصروف ہے۔ اس لیے ان سے پہلے سی محبت نہیں کر سکتا اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ فیصلہ اس نے کسی شدید جذباتی کرب کے عالم میں سنایا ہے بلکہ اس طرح جیسے کوئی کسی ملازمت میں تبادلے کی خبر سناتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب تبادلہ ترقی پر ہوا ہو، اب بھی دل کش ہے تراحسن مگر کیا کیجیے۔
میرا خیال ہے کہ پوری اردو شاعری سفاکی میں اس مصرعے کاجواب نہیں دکھا سکتی۔ اسے پڑھ کرمیرادل کسی غیر انسانی چیز کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ بالکل ایساہی اثر نثر کے ایک فقرے سے ہوا۔ اقبال نے کسری آدمی کی پیدا کی ہوئی تہذیب پر ایک جگہ اعتراض کیا ہے کہ یہ ترقی ورقی تو سب ٹھیک ہے مگر،
ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔
اقبال کے ایک مداح جو اردو کے خاصے اچھے نقاد سمجھے جاتے ہیں، ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ’’مشینوں کی حکومت دل کی موت سہی۔‘‘ لیکن انسان کی اس ترقی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ذرااس ’’سہی‘‘ کو دیکھیےگا اور یہ ذکر دل کی موت کاہے۔ یقین کیجیے کہ ۱۹۴۷ کے فسادات کی مجموعی تباہ کاری بھی میرے دل پر ہولناکی کا اتنا بڑا تاثر نہ ڈال سکی جتنا اس ایک مصرعے اور ایک فقرے میں موجود ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ میرا کوئی ذاتی کامپلکس ہو، اس لیے آپ تو فیض صاحب کے مصرعے کو دیکھیے۔ ’’اب بھی دل کش ہے تراحسن‘‘ اس طرح کہاہے کہ ہاں اصلی مزہ تو رقیب نے لوٹ لیا مگر خیر، یعنی ہم تواس کے باوجود جیسی چلی آتی ہے چلاتے رہتے۔ مگر کیا کریں آخر دنیا کے دوسرے دھندے بھی ہیں۔
بات بھی ٹھیک ہے۔ خودپرستی کی تسکین کرنی ہے تو ایک عورت ہی سے کیوں کی جائے۔ ساری دنیاکی تالیاں کیوں نہ وصول کی جائیں۔ نقاد لوگ کہتے ہیں فیض کی یہ نظم نہ صرف اردو شاعری، بلکہ عشق کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتنی شان دار بات ہے کہ آدمی اپنی محبوبہ کو دنیا کے بھلے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ ہے نئی انسانیت۔ اچھا تو کیا محبوبہ کو چھوڑ کر یہ عاشق صاحب کنوارے مر جائیں گے؟ اور سارے انسان کنوارے مر گئے تو انسانیت کیا ہائیڈروجن بم سے اپنا سر پھوڑےگی۔ لیکن نقادوں کو ایسے سوالوں سے غرض نہیں۔ انہیں بھی شاعر کی طرح اپنی دکان چمکانی ہے۔ نقادوں کی دکان داری اور شاعر کی رومانی خودپرستی کے طفیل یہ انداز نظر بڑھتا ہی جائےگا۔ اب ساحر بھی اپنی محبوبہ کو اسی طرح چھوڑ دیں گے۔ ان کی محبوبہ بےچاری کبھی رقیب کے ساتھ نہیں گئی، اس لیے یہ ذرا جذباتی ہو رہے ہیں،
نہیں نہیں مجھے یوں ملتفت نظر سے نہ دیکھ
نہیں نہیں مجھے اب تاب نغمہ پیرائی
مراجنون وفا ہے زوال آمادہ
شکست ہو گیا تیرافسون زیبائی
اور ان کے ساتھ جاں نثار اختر بھی بھاگیں گے،
یہ دور ہے جنگی نغموں کے افلاک سے ٹکراجانے کا
یہ وقت نہیں ہے الفت کے رنگین ترانے گانے کا
اور اختر الایمان جیسامحبت سے لہولہان شاعر بھی،
پھر مراخون مچلتا ہے ارادے بن کر
پھر کوئی منزل دشوار بلاتی ہے مجھے
پھر کہیں دشت و جبل ڈھونڈ رہے ہیں مجھ کو
پھر کہیں دور سے آواز سی آتی ہے مجھے
اڑ چلا اوس کی مانند ستاروں کاہجوم
آج میں تیرے شبستاں سے چلا جاؤں گا
مجموعے پر مجموعے دیکھتے چلے جائیے، ہر جگہ یہی جانے جانے کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ وداع، گریز، سفر، مسافر، غم دوراں، غم دنیا، غم انساں۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، پیارے شادی کروگے یا نہیں؟ شادی کرنی ہے تو محبوبہ کیا بری ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ رومانی محبت ہے۔ اس کی شریعت میں شادی حرام ہے، کیوں کہ شادی اپنی فطرت کو، جنسی زندگی کو، اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے کہ ہم آدمی ہیں۔ شہزادہ شہزادی، دنیا کی بگڑی بنانے والے گرتے ہوئے آسمان کو پدری کی طرح اپنے پیروں پر روکنے والے، دردمندوں اور غریبوں کی حمایت میں اپنا گھر پھونکنے والے، پوری انسانیت پراپنے احسان کا چھپر رکھنے والے نہیں ہیں۔
یاد رکھیے یہ سب رومانی خودپرستی کی شکلیں ہیں۔ آپ مار باندھ کران میں سے کسی کی شادی کر دیجیے۔ یہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا کی بگڑی بنانے بھاگ جائیں گے (ابھی تازہ اطلاع ہے کہ اردو اسکرین کے محبوب ترین رومانی ہیرو دلیپ کمار صاحب نے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ ان کے نزدیک بیوی سے کافی کی ایک پیالی بہتر ہے) اور جب دنیاکی بگڑی بننے کی بجائے اپنے گھر کے بگڑنے کی خبر ملےگی تو اسے بھی اپنی رومانی خودپرستی کے کالر میں ایک پھول کی طرح سجالیں گے۔ ’’زیر لب‘‘ والی صفیہ نے ہمیں یہ اندوہناک داستان بہت تفصیل سے سنائی ہے۔ جو شریف ایسا نہیں کر سکیں گے وہ شادی سے ایک اور طرح گریز کریں گے کہ بیوی کو بچوں کی ماں تو بنا دیں گے مگر اسے اپنے مقدس رومانی شعور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس طرح شوہر اور باپ الگ رہ جائےگا اور رومانی آدمی الگ۔ شوہر بچے پیدا کرےگا، بچے پالےگا اور رومانی آدمی اپنی شہزادی کی شان میں نظمیں لکھےگا۔ اب بیوی بھی اس توہین کا بدلہ لےگی کہ بچے تو جن دےگی مگر خودجنسی طور پر سرد ہو جائےگی۔
میراجی کا’’وہ ساگر‘‘ یاد کیجیے جو بہتے مسافر کو آگے بہانے کے بجائے صرف جھکولے دیے جاتا ہے۔ پھر اس ادھورے اور اس لیے ناپاک جنسی تجربے سے بیزاری کی وہ کیفیت پیدا ہوگی جو شوہرکو زہریلی ناگن کی طرح ڈسےگی۔ اب اس بیزار جوڑے میں صرف ایک ہی رشتہ ہوگا، بینک بیلنس۔ یہ ہے ہمارے رومانی کی گھریلو زندگی۔ اس گھریلو زندگی سے بہت جلد وہ بلا پیدا ہوگی جسے دیکھ کر اردو روزناموں کے معصوم مراسلہ نگار حیرت سے پوچھیں گے، آخر ہماری عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب تتلیاں کیوں بنتی جا رہی ہیں؟
رومانیت فیض صاحب کی شاعری کااصلی موضوع ہے۔ جنسی رومانیت، سیاسی رومانیت۔ ان کی انسان پرستی کی ساری قدریں اسی سے پیدا ہوتی ہیں اور اسی لیے غیرانسانی ہیں۔ جہاں کہیں وہ شعوری طور پر ذرابے خبر ہوتے ہیں، اس غیرانسانی انسان پرستی کا مکروہ چہرہ ان کی حسین غنائیت کے پیچھے سے جھانکنے لگتا ہے، پیوکہ مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید۔ ذرا’’مفت لگادی ہے‘‘ کا ٹکڑا ملاحظہ کیجیے اور یہ خطاب انسانیت سے ہو رہا ہے۔ کسی پیغمبر نے بھی امت پر اس طرح احسان کا ہے کو دھرا ہوگا۔ اس کے برعکس جب ایک حقیقی آدمی انسانیت کے سچے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے تو اس کا لہجہ یہ ہوتا ہے،
ہر منظر، ہر انساں کی دیا، اور میٹھا جادو عورت کا
ایک پل کو ہمارے بس میں ہے، پل بیتاسب مٹ جائےگا
اس ایک جھلک کو چھچھلتی نظر سے دیکھ کے جی بھر لینے دو
(چل چلاؤ۔۔۔ میراجی)
ن م راشد صاحب فرماتے ہیں، ’’فیض اپنے تصورات سے اپنے لیے خالص حسن کا ایک دل کش بہشت پیدا کرنا جانتا ہے۔۔۔ فیض کی ابتدائی شاعری اس طلسمی حقیقت سے گریز کی داستان ہے۔‘‘ لیکن اس کے بعد تمام نقادوں کی طرح وہ بھی دھوکا کھاتے ہیں، ’’اس نے حسن ورومان کے سنہری پردوں کے اس پار حقیقت کی ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ وہ عہد جدید کی شیطنت کو ضرور ’عریاں ‘کرتا ہے۔‘‘ تعجب ہے کہ ’’ماورا‘‘ کے شاعر کو یہ احساس نہیں کہ عہد جدید کی سب سے بڑی شیطنت خود رومانیت ہے اور فیض نے حسن ورومان کے سنہری پردوں کے اس پار جو حقیقت دیکھی ہے، وہ بھی رومان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کسری انسان کی تقدیر ہے۔ وہ ہر حقیقت کو ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہے، خودپرستی کے زاویے سے۔ محبت کا مقصد اپنی تکمیل ہے، سیاست کا مقصد اپنی تزئین،
اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل
ہر داغ ہے اس دل میں بہ جز داغ ندامت
لیکن یہ خود پرست رومانیت خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کی حیثیت صرف ایک آکاس بیل کی ہے جس کی جڑ نہیں ہوتی۔ جڑ تو حقیقی آدمی کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ خود پرست بلا حقیقی آدمی کے خون سے اپنی آبیاری کرے ی۔ یہی رومانی آدمی کا کرب ہے۔ رومانی آدمی جب یہ کرب برداشت کرنا سیکھ جائےگا تب وہ عظیم انسان بن جائےگا، جو فیض کی نظم’’دوعشق‘‘ کا ہیرو ہے۔ یہ نظم بہت خوبی سے دکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر تجربے کو رومانیت کس طرح اپنے سینے کا تمغہ بنا سکتی ہے۔ تمغے کے ذکر پر خدا جانے کیوں مجھے مجاز یاد آ گئے، ’’کرنل نہیں ہوں خان بہادر نہیں ہوں میں‘‘ والے مجاز۔ یہ ایک رومانی کا دوسرے رومانی پر اعتراض ہے مگر دونوں کی قسمیں جدا جدا ہیں۔ مجاز رومانی تو ہے مگر نسبتاً بے ضرر قسم کا۔ اس سے اگر کسی کو ضرر پہنچ سکتا ہے تو صرف اسی کو۔ یہ رومانی کی وہ قسم ہے جو ہمیشہ خودکشی کرتی ہے (اس سوسائٹی میں آدمیوں کی صرف دو قسمیں ہیں، قتل کرنے والے اور خود کشی کرنے والے۔ بالزاک۔)
اردو ادب کی تاریخ کا یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک پوری نسل کی تباہی کی مکمل داستان دوبھائی بہنوں نے ہمیں سنادی۔ بھائی نے اپنی شاعری میں، بہن نے اپنے خطوں میں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں مجاز اور صفیہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ دونوں بھی رومانی تھے مگر خودکشی کرنے والے۔ صفیہ کی ہول ناک داستان کا تجزیہ میں کسی اور وقت کروں گا۔ اس وقت صرف مجاز کو دیکھیے۔ لیکن پہلے رومانیت کی صدرنگ شکلوں میں ہمیں ان کی رومانیت کی قسم متعین کرنی پڑےگی۔ پتا نہیں آپ مضمون پڑھتے پڑھتے بور ہوئے یا نہیں لیکن لکھتے لکھتے ضرور تھک چکا ہوں۔ اس لیے آپ مجھے تو تھوڑا دم لینے دیجیے اور ۱۹۳۶ کی نسل کا رزمیہ اٹھاکر رومانیت کی مختلف شکلوں کا مطالعہ کیجیے۔ میری مراد عصمت کی ’’ٹیڑھی لکیر‘‘ سے ہے۔ اس کے بعد ہم آسانی سے مجاز کی رومانیت کو متعین کر سکیں گے۔
’’یہ لوگ بس زندگی میں ایک بار اپنے طبقے کو چھوڑ کر عشق رچا لیتے ہیں، خواہ وہ یک طرفہ چیز ہو۔ مگر ناکامی لازمی نتیجہ ہے۔ اور شاید ایساعشق کرکے ناکام ہونا ہی یہ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ یہ درمیانہ طبقے کا کم حیثیت لڑکا چھانٹ کر اپنے آسودہ حال پروفیسر کی لڑکیوں یا جس سیٹھ کے دفتر میں وہ چالیس روپے کا نوکر ہو، اس کی اکلوتی لڑکی پر عاشق ہو بیٹھتا ہے۔ اگر اچانک کبھی ایسے عشق میں کامیاب ہوجائے تو بھونچکا سارہ جاتا ہے۔ اسے بھگا کرلے جانے سے بھی خواب چور چور ہو جاتا ہے۔ دریا میں ڈوب کر بھی پیاسا رہ جاتا ہے۔ وہ تو عشق صرف نام رہنے کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کے قصے اپنی نئی دلہن کو ٹھنڈی سانسیں بھر بھر کر سنایا کرے۔
رنڈی کو اپنی بیوی کا رقیب بنانے میں وہ ہتک محسوس کرتا ہے۔ نچلے طبقے کا ہوتے ہوئے بھی وہ عشق جیسے بلند جذبے کو بلندی ہی پر رکھنا چاہتا ہے۔ اپنی بیوی سے کبھی محبت نہیں کرتا مگر اس کے جنے ہوئے کیڑوں کی پرورش میں انسان سے چرخا بن جاتا ہے۔ اس کی بیماری پر ہاتھ پیر پھلا لیتا ہے اور ذرا روٹھ جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کر منا لیتا ہے۔ اپنی محبوبہ کارتبہ بہت بلند سمجھتا ہے مگر اپنی بیوی سے کم معصوم اور پارسا جانتا ہے۔
اس محبوبہ کو وہ روحانی طمانیت کے لیے اپنی شخصیت میں چھپا لیتا ہے۔ اگر اصلی نہیں تو خیالی ہی سہی۔ وہ ہر طرح اس سے لطف اندوز ہو لیتا ہے۔ جب بیوی حاملہ ہوتی ہے یا میکے چلی جاتی ہے تو اسے بڑی احتیاط سے نکال کر عشق حقیقی سے جی بہلاتا ہے اور یہ خیالی رقیب دور بچھڑی ہوئی بیوی کے سینے میں رقابت کی آگ بھڑکاکراس کی محبت کو اور پختہ کر دیتا ہے۔‘‘ (ٹیڑھی لکیرص ۳۳)
اچھا یہ تو ہوا ۱۹۳۶ والی سوسائٹی کا مردانہ حصہ۔ اب زنانہ حصہ دیکھیے،
’’تعلیم یافتہ لڑکیوں کی مانگ بڑھی مگر اس تیزی سے نہیں جس تیزی سے تعداد بڑھی۔ جب ایک میٹرک پاس لڑکی عنقا سمجھی جاتی تھی، اب گلی گلی گریجویٹ اگ آئیں۔ شادیوں کے بازار میں بڑی افراتفری مچ گئی۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کے لیے کم از کم آئی سی ایس، یاپی سی ایس توہو۔ کاش گورنمنٹ لڑکیوں کی تعداد دیکھ کر افسروں کا تقرر کرتی تو یہ مصیبت کیوں نازل ہوتی۔ یہ گنے چنے افسر تو اونٹ کی داڑھ میں زیرہ بن کر رہ گئے۔ جس نے اونچی بولی لگائی، وہی لے اڑا۔ نتیجہ یہ ہواکہ گریجویٹ اور تعلیم یافتہ لڑکیاں اس انتظار میں کہ کب گورنمنٹ افسر برسیں اور وہ سمیٹ لیں، مختلف شعبوں میں نوکر ہو گئیں۔
اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ افسروں کی تعداد کم رہی تو کلرک، بدقسمت اسکول ماسٹر، ناکام اور اجڑے ہوئے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوئے۔ وہ تو اور بھی شدت سے پیدا ہوئے۔ اب ان بے چاروں کے پاس صرف دو راستے رہ گئے۔ یاتو جاہل لڑکیوں سے سر پھوڑ لیں یا امیر اور تعلیم یافتہ لڑکیوں سے تخیلی عشق کرکے ان کی یاد میں زندگی گرا دیں۔ جنہوں نے دل پر پتھر رکھ کر سر پھوڑ لیا، ان کی روحیں بھی جیون ساتھی کی تلاش میں بھٹکیں گی۔ زندگی بھر ہم خیال، ہم مذاق بیوی کا ارمان دل میں کچوکے مارتا رہا۔‘‘ (ہیروئین ازعصمت چغتائی)
اب ان دونوں حصوں کو ملائیے اور ٖغور سے دیکھیے کہ ان میں مجاز کہاں ہیں۔ صرف مجاز ہی نہیں بلکہ اردو کے وہ تمام شاعر جو ۱۹۳۶کی اس سوسائٹی سے برآمد ہوئے۔ انہیں کے ذریعے ہم اس سوسائٹی کا تجزیہ کر سکیں گے۔ میں جب اس نقطہ نظر سے نظم کے نئے شاعروں پر نظر ڈالتا ہوں تو ان میں سر فہرست یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ مجاز، ساحر، اخترالایمان، جاں نثار اختر اور قتیل شفائی۔ نئی نظم کے دوسرے قابل ذکر شعر امختار صدیقی، یوسف ظفر، قیوم نظر، سلام مچھلی شہری، جذبی، اختر انصاری ہیں۔ ہاں اس فہرست کا ایک بہت وقیع نام تو میں بھول ہی گیا۔ حامد عزیز مدنی۔ مگر افسوس کہ یہ لوگ اس تجزیے میں ہماری کوئی مدد نہیں کرتے۔ جہاں تک شاعرانہ خوبیوں کاتعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نئی اردو شاعری میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ میں ان پر کسی اور زاویے سے آئندہ اپنے کسی مضمون میں روشنی ڈالوں گا مگر فی الحال وہ ہمارے کام کے نہیں۔ اس لیے انہیں ابھی شاعری کرنے کے لیے چھوڑ دیجیے۔
مجاز کا معاملہ بالکل صاف ہے۔ علی گڑھ کی نمائش پر نظمیں لکھتے ہوئے یونیورسٹی سے نکلے۔ بیچ میں ایک آدھ’’نرس‘‘ سے فلرٹیشن کیا اور آخر میں کسی ’’شہنازلالہ رخ‘‘ کے کاشانے پر پہنچ گئے۔ یہ محترمہ مجاز پر مہربان ہوئیں۔ مجاز ان پر عاشق ہو گئے۔ پھر سلسلہ چل نکلا۔ بیچ میں جدائی کا مرحلہ آیا۔ آپس میں جھوٹے سچے پیمان ہوئے اور مجاز اس کے کا شانے سے نکل کر جگمگاتی جاگتی سڑکوں پر آوارہ پھرنے لگے۔ اس آوارگی میں کئی بار عہد وفا توڑ دینے پر نیت ڈانواں ڈول ہوئی مگر ’’شہر یاروں‘‘ کی رقابت میں جو مزہ آیا تھا اسے بھول نہ سکے۔ ضد پیداہوئی کہ یاتو کھائیں گے گھی سے، ورنہ جائیں گے جی سے۔ گھی چوں کہ شہریاروں کے قبضے میں تھا اس لیے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ شبستان پھونک دینے کے ارادے باندھے۔
ان کے قاری بھی انہیں مرحلوں سے گزر رہے تھے۔ ان کے طفیل ایک جماعت کا احساس ہونے لگا۔ کامیابی کی امید پیدا ہوئی۔ محبوبہ کو آواز دی کہ معرکہ گرم ہونے والاہے تو بھی باہر نکل آ۔ (ان کے قاری نے بھی یہی کیا) لیکن محبوبہ مجبور تھی یا ممکن ہے زیور کپڑے کی خریداری میں مصروف ہو۔ بزم دلبراں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ نگاران لکھنؤ خاموش رہے۔ شہر طرب علی گڑھ، ایوان خوباں الہ آباد، معبد حسن وعشق دہلی پر سناٹا چھا گیا۔ مایوسی نے سب کچھ بھلا دینے کی کوشش کی، مگر پہلو میں دبا ہوا نشتر زہر آگیں اپنا کام کرتا رہا۔ محبوبہ کو جب خریداری سے فرصت ملی یا مجبوری رفع ہوئی تو غریب دوڑی دوڑی آئی مگر مجاز میں اب کیا دھرا تھا۔ اب مرے پاس جو آئی ہو تو کیا آئی ہو۔ مجاز اب خود اپنا بھوت بن چکا تھا۔ اس نے چیخیں مارنی شروع کر دیں،
میرے سایے سے ڈرو تم مری قربت سے ڈرو
اپنی جرأت کی قسم، اب مری جرأت سے ڈرو
تم لطافت ہو اگر میری لطافت سے ڈرو
میرے دعوؤں سے ڈرو میری محبت سے ڈرو
آخری خبر مجموعے کے بجائے اخباروں میں چھپی۔ مجاز ایک شراب خانے کی چھت پر سردی سے سکڑ کر مر گئے۔ مطرب بزم، دلبراں کا انجام! (قاری کو بھی ساتھ ساتھ چلائیے۔ کچھ مر گئے، کچھ نے خودکشی کرلی۔ کچھ پاگل ہوئے، کچھ نے محبوبہ کو قتل کر دیا۔ جو باقی بچ گئے وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر انشورنس کمپنی میں ملازم ہو گئے۔)
ساحر کو دیکھیے۔ محبت ایسی ملی جو ان پر پھول چڑھاتی تھی (شہزادہ شہزادی کے بجائے دیوی دیوتا) ماں باپ کو خبر ہوئی۔ ملناجلنا بند۔ لڑکی کی شادی کی جائےگی۔ ساحر نے صاف کہہ دیا، تم میں ہمت ہو تو دنیا سے بغاوت کر دو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ اس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ تم ہی مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ساحر یہاں قائل ہو گئے، کس طرح تم کو بنا لوں میں شریک زندگی، میں تو اپنی زندگی کا بار اٹھا سکتا نہیں۔ محبوبہ نے کہا۔ اچھا تو جائیے تشریف لے جائیے۔ انہیں بھی غصہ آیا۔ اپنے آپ پر کم، محبوبہ پر زیادہ۔ (صفیہ لکھتی ہے، ’’تم اپنے آپ سے محبت کرنا خوب جانتے ہو۔ آخر شاعر ہونا!‘‘ شاعر نہیں صفیہ! خودپرست رومانی) اسے طعنہ دیا کہ تو چمکتی ہوئی کار پر ریجھ گئی ہے اور چلے آئے۔
کچھ دن بعد خبر لگی کہ محبوبہ اداس اداس رہتی ہے۔ خود پرستی کو تسکین ہوئی۔ دل ذرانرم پڑا۔ مشورہ دیا کہ تم اپنے حسن کی رعنائیوں پہ رحم کرو۔ مری حیات کی غم گینیوں کا غم نہ کرو۔ یہ محبت اور وفا کا چکر ڈھکوسلا ہے۔ مجھے بھول جاؤ (رومانی ایثار) مجھے قسم ہے مری دکھ بھری جوانی کی۔ میں خوش ہوں میری محبت کے پھول ٹھکرا دو۔ میں اپنی روح کی ہر اک خوشی مٹا لوں گا۔ مگر تمہاری مسرت مٹا نہیں سکتا۔ محبوبہ کی غیرت بھی جوش مارتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بھی مرجاؤں گی۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ساحر کو ایک عجیب جواب سوجھتا ہے،
تمہارے غم کے سوا اور بھی تو غم ہیں مجھے
نجات جن سے میں اک لمحہ پا نہیں سکتا
فیض کی ’’مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ‘‘ کا اثر نمایاں ہے مگر فیض جیسی سفاکی نہیں۔ پوری نظم تیز جذبات سے بھبک رہی ہے۔ ساحر بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے ایک بنا بنایا جھوٹا رومانی سانچہ مل گیا جس میں وہ اپنی روح کو بند کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر کاآدمی چیخ چیخ کراحتجاج کر رہا ہے۔ ساحر اسے سمجھا بجھا کرانسان پرستی کے دھڑے پر لگانا چاہتا ہے۔ اس کے رومانی پیش رو اسے یہی سکھا چکے ہیں (شہروں میں عشق و محبت بہت جلدی پروان چڑھتی ہے، کیوں کہ محبت کے بنے بنائے سانچے ناولوں میں مل جاتے ہیں۔ استاں دال) ساحر نے یہ بنا بنایا سانچہ فیض سے لیا،
یہ اونچے اونچے مکانوں کی ڈیوڑھیوں کے تلے
ہر ایک گام پہ بھوکے بھکاریوں کی صدا
ہر ایک گھر میں یہ افلاس اور بھوک کا شور
ہر ایک سمت یہ انسانیت کی آہ و بکا
یہ غم بہت ہیں مری زندگی مٹانے کو
اداس رہ کے مرے دل اور رنج نہ دو
(تقابلی مطالعے کے لیے پھر فیض کو یاد کیجیے۔ وہ کہتے ہیں،’’اب بھی دل کش ہے تراحسن مگر کیا کیجے‘‘) محبوبہ چپ ہو جاتی ہے۔ اب اس بنتے ہوئے انسان پرست کا حال درجہ بہ درجہ دیکھیے۔ محبوبہ سے جدا ہو کر وہ نت نئی باتیں سوچتا ہے، نت نئے منصوبے تیار کرتا ہے۔ ایک منصوبہ یہ ہے،
سوچتا ہوں کہ محبت نہ رہےگی زندہ
بیش ازاں وقت کہ سڑ جائے یہ گلتی ہوئی لاش
یہی بہتر ہے کہ بیگانۂ الفت ہوکر
اپنے سینے میں کروں جذبۂ نفرت کی تلاش
جذبۂ نفرت کی تلاش سوسائٹی کے خلاف ہے۔ مقابلے کے لیے پھر فیض کو دیکھیے۔ سوسائٹی فیض کو دار پر چڑھانا چاہتی ہے۔ اس سے ان کی خود پرستی کو تسکین ہوتی ہے۔ اس لیے وہ دار کو اپنی عظمت کا پرچم بنا لیتے ہیں اور کاندھے پر لادے لادے پھرتے ہیں۔ ساحر میں ابھی یہ عظمت پیدانہیں ہوئی۔ ابھی وہ پکا انسانیت پرست نہیں بنا۔ اس لیے بار بار چلاتا ہے،
میں نے ہر چند غم عشق کو کھونا چاہا
غم الفت غم دنیا میں سمونا چاہا
دل نے دنیا کے ہر اک درد کو اپنا تو لیا
مضمحل روح کو انداز جنوں مل نہ سکا
رومانی آدمی کی اس چیخ وپکار پر بالکل دھیان نہ دھریے۔ یہ چوں کہ پورے آدمی کی طرح حیات کی بے کراں قوت کے آگے اپنی خوشی سے سر جھکانا نہیں چاہتا ہے اور محبت کو، جنسی جذبے کوصرف شخصی چیز سمجھتا ہے، اس لیے بہت جلد اس چیخ وپکار سے تھک جائےگا،
عجیب عالم افسردگی ہے رو بہ فروغ
نہ اب نظر کو تقاضا نہ دل تمنائی
تری نظر، ترے گیسو، تری جبیں، ترے لب
مری اداس طبیعت ہے سب سے اکتائی
اور اس کے ساتھ ایک شعر ہے،
ہر ایک ہاتھ میں لے کر ہزار آئینے
حیات بند دریچوں سے بھی گزر آئی
لطف یہ ہے کہ ان تمام آئینوں میں صرف ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ حیات سے اکتائی ہوئی رومانیت کا چہرہ! اب اس اکتاہٹ میں ساحر کے ’’میں‘‘ کو نئے نئے کھیل سوجھیں گے۔ انقلاب، تخریب، قتل وغارت، مزدوروں کا جلسہ اور پھر طوائف بازی بھی۔ لیکن کسی چیز میں مزہ نہیں آئےگا۔ اسی حالت میں ایک نیا واقعہ پیش آتا ہے۔ ساحر کے ’’میں‘‘ کو ایک نئی لڑکی ملتی ہے۔ یہ بھی پہلی والی لڑکی کی طرح ’’اونچے مکان‘‘ والی لڑکی ہے۔ وہ اسے ایک دفعہ بھگت چکا ہے مگر خودپرستی کو ایسی لڑکی کے سوا تسکین بھی تو نہیں ہوتی، ا س لیے پھر بھگتےگا،
تری چپ چاپ نگاہوں کو سلگتا پاکر
میری بیزار طبیعت کو بھی پیار آ ہی گیا
گھبراؤ نہیں رومانی! ابھی بیزار طبیعت اور بیزار ہوگی۔ تین چار نظموں ہی کے بعد ہم دیکھتے ہیں،
ابھی روشن ہیں ترے گرم شبستاں کے دیے
آج میں موت کے غاروں میں اترجاؤں گا
اور دم توڑتی بتی کے دھویں کے ہم راہ
سرحد مرگ مسلسل سے گزر جاؤں گا
سرحد مرگ مسلسل سے مراد ہے زندگی۔ یہ حضرت خودکشی کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ذاتی نظمیں ختم، سیاسی نظمیں شروع،
تم سے قوت لے کر ساتھی، تم کو راہ دکھاؤں گا
تم پرچم لہرانا ساتھ، میں بربط پر گاؤں گا
نتیجہ اندروالے ساحر نے خودکشی کر لی۔ اب صرف باہر والا آدھاآدمی رہ گیا جو بربط پر نغمہ گانا چاہتا ہے (رومانی فنکار) یہ آدھاآ دمی ۱۹۴۷میں بربط پھینک کر بندوق مانگےگا (رومانی انقلابی) اور جب بندوق سے کوئی نتیجہ نہ نکلتے دیکھےگا تو فلمی گیت گانے لگےگا (میں نے جو گیت ترے پیار کی خاطر لکھے) اس کا قاری بھی یہی کرےگا۔ فلمی گیت نہ سہی، سرکاری ملازمت سہی۔ یہ بھی نہ سہی تو کچھ اور سہی۔ ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں۔ جاں نثار کو دیکھیے، کون سا گیت سنوگی انجم؟ یہ بھی رومانی، وہ بھی رومانی۔ وہ گیت سنیں گی، یہ گیت سنائیں گے۔ اس طرح شاعر کی جنت تعمیر ہوگی۔ اس دوران میں صاحب زادی کے نکاح کا پیغام آ گیا۔ جنگ کی تعمیر بند ہو گئی،
زندگی ہوگی محبت کی کہانی تیری
مسکرائےگی دلہن بن کے جوانی تیری
میں کہیں دور بہت دور چلا جاؤں گا
اچھا صاحب دور گئے۔ اب تصویر کی مصیبت ہے۔ مصیبت سے چھٹکارا پانے کا نسخہ غالب پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ اک گو نہ بے خودی کے لیے شراب۔ چنانچہ اسی نسخے پر عمل کیا گیا (رومانی مشغلہ)
اور پیتا ہوں تو پینے نہیں دیتا کوئی
اب کسی طرح بھی جینے نہیں دیتا کوئی
’’گزرے ہوئے لمحات میں‘‘ جاں نثار کا’’میں‘‘ اپنی ناکامی کی وجہ بتاتا ہے۔ محبوبہ امیر تھی۔ یہ غریب تھے (عصمت کے اقتباسات یاد کرتے چلیے۔) اس نظم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عاشق صاحب غم ہجر اور اکثر تو شراب نوشی کے سبب بیمار ہو گئے۔ اس بیماری میں زہرہ نے ان کے عیادت کی۔ یہ ایک شادی شدہ خاتون ہیں،
زہرہ نے بہت کی ترے بیمار کی خدمت
بھولے سے بھی جھپکی نہ پلک جس کی کسی رات
وہ جس نے کسی اور کی ہو کر مجھے چاہا
وہ جس کی وفاؤں نے زلیخا کو کیا مات
سلمیٰ کے بعد زہرہ رومانی عورت کی ایک نئی شکل ہے۔ شادی شدہ، شوہر سے غیرمطمئن۔ میراجی کے الفاظ میں زہریلی ناگن، چڑیل۔ میراجی کی مدد سے شوہر کو بھی متعین کیجیے۔ دن کاسایہ، ہنہناتی ہوئی ہنسی والا بھوت۔ دونوں انسان کی کسری شکلیں۔ اب یہ چڑیل اپنے بھوت کو چھوڑ کر اپنے خوابوں کے شہزادے کے پاس آئی ہے۔ شہزادے کو وہ اپنی پہلی شہزادی کی ہم شکل نظر آئےگی کیوں کہ دونوں کی روح ایک ہے۔ خود پرستی۔ مرد کو پھول کی طرح اپنے جوڑے میں سجانے کا جذبہ۔ شہزادے کو بھی اور کیا چاہیے۔ وہ بھی کئی کئی شہزادیوں کو اپنے اوپر مرتا دیکھ کر پھولا نہ سمائےگا اور فوراً پہلی شہزادی کو تار دےگا کہ میری عظمت دیکھنا۔ زہرہ کو بھی شہزادے کی پہلی محبتوں سے کوئی الجھن نہ ہوگی۔ یہ تو اسے بڑا شان دار شہزادہ ملا۔ اس لیے وہ شہزادے کی پہلی محبوبہ کی ہم شکل ہونے پر جلنے کے بجائے مسرت کا اظہار کرےگی۔ باقی پلاٹ صاف ہے۔
انجم کی شادی ہو چکی (اس کے شوہر کا انجام سوچیے۔ یہ وہ ساگر ہے جو جھکولے دیتا ہے اور بہاتا نہیں۔ اس لیے اس کا شوہر بھی دن کا سایہ بن جائےگا۔ چھوت کی بیماری کی طرح یہ وبا پوری سوسائٹی میں اسی طرح پھیلتی ہے۔ ) اور زہرہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جاں نثار کی نظموں کا’’میں‘‘ ہے۔ اس کی خود اطمینانی دیکھیے،
ہو کچھ زندگی، موت، فرقت، وصال
محبت بہر کیف ہے کامیاب
’’بہر کیف ہے کامیاب‘‘ کا ٹکڑا ملاحظہ فرمایئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے زندگی کا تمام مسائل کا حل سوچ لیا۔ صرف دلچسپی کے لیے زہرہ کی شان میں ایک قصیدہ بھی سن لیجیے،
ہزاروں بار دہرایا گیا ہے لفظ الفت کا
میں تیرے سامنے اس لفظ کو دہرا نہیں سکتا
مگر اس دل میں کچھ جذبات ہیں جن کی تو ملکہ ہے
وہ کیا جذبات ہیں میرے تجھے سمجھا نہیں سکتا
کوئی ظالم مشیت روک لیتی ہے مجھے ورنہ
میں تیرے واسطے کس چیز کو ٹھکرا نہیں سکتا
مگر میں زندگی بھر صرف تیرے گیت گاؤں گا
اور ایسے گیت جو دنیا میں کوئی گا نہیں سکتا
مگر زہرہ بڑی تجربہ کار ہے۔ وہ جانتی ہے کہ مرد گیت گانے کے علاوہ ایک کام اور بھی کرتا ہے اور یہ کام نہ کر سکے تو ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے اور حسن اتفاق سے وہ اپنے شہزادے کی بیزاری کا ایک لمحہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ بیزاری بھی دیکھنے کی چیز ہے،
ہو سکی دنیا نہ مجھ سے مستفید
مجھ سے وابستہ تھی کس کس کی امید
آج ہر احساس ہے کوسوں بعید
یعنی غصہ اس بات پر آیا ہے کہ بدنصیب دنیا نے آپ کی ذات ہمہ صفات سے کچھ ’’استفادہ‘‘ نہیں کیا۔ خودپرستی ایسی توہو۔ اس کے بعد یہ خودپرستی فلسفے کا روپ دھارتی ہے اور دنیا کے خلاف یہ نتائج مرتب کرتی ہے،
عشق کیا ہے؟ ایک ذہنی اضطراب
حسن کیا ہے؟ جاگتی آنکھوں کا خواب
علم کیا ہے؟ اک سوال بے جواب
ہر طرف بغض و عداوت قتل و جنگ
کھا چکی انصاف کی میزان زنگ
لٹ چکا انسانیت کا نام و ننگ
نظم کا ٹیپ کا مصرع ہے، دوست سب کچھ بھول جانے دے مجھے۔ ساحر کے آدمی نے خودکشی کی تھی۔ جاں نثار کا آدمی بھول گیا۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس لیے نتیجہ لازمی طور پر یہی نکلنا چاہیے،
کچھ محبت کے سوا اور بھی سوچا ہوتا
زندگی صرف محبت تو نہیں ہے انجم
(فیض اور ساحر کو پھر تقابل میں رکھ کر دیکھیے۔ اب ایک ہی سانچہ اپنی تکرار کرتا چلا جائےگا) صرف یہی نہیں۔ یہ بھی کہ،
اب یہ طوفان ادارہنے دے
یہ محبت کی بلارہنے دے
(’’طوفان ادا‘‘ کے معنی ہیں کہ ’’محبوبہ‘‘ رنڈی معلوم ہونے لگی۔)
’’زندگی صرف محبت تو نہیں ہے انجم۔‘‘ سلاسل کی آخری نظم ہے جس میں جاں نثار کی شاعری کا’’میں‘‘ کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ اس کے آگے ’’بیدار ہے انسان‘‘، ’’خاتمہ کلام‘‘، ’’تلوار اٹھا۔‘‘ ساحر میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ساحر نے بندوق مانگی تھی (یہاں جاں نثار گھٹ گئے، شاعر بھی تو ساحر سے چھوٹے ہیں ) اس کے بعد زبیر فاطمہ’’حرف آشنا‘‘ کے دیباچے میں لکھتی ہیں،’’سناہے اختر اب بمبئی میں آسودہ زندگی بسر کرتے ہیں۔‘‘
اختر الایمان کی شاعری ک اپلاٹ بہت ہی سادہ ہے، محبت۔ پھر وہی شادی کا جھگڑا پڑا۔ عاشق کے پاس سب کچھ ہے سوائے زر نقد کے۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ عاشق پیسہ کمانے جائے اور محبوبہ واپسی کا انتظار کرے۔ عاشق پیسہ کمانے جاتا ہے۔ آج میں تیرے شبستاں سے چلا جاؤں گا (تقابلی مطالعہ جاں نثار، ساحر) لیکن پیسہ کمانا آسان تھوڑی ہے۔ روز دفتروں کے چکر کاٹتے کاٹتے جدائی کا درد بھی کھو جاتا ہے۔ ہستی بےرنگ معلوم ہونے لگتی ہے۔
نتیجہ: جمود۔
تم سے بے رنگی ہستی کا گلہ کرنا تھا
ساقی و بادہ نہیں جام ولب جو بھی نہیں
تم سے کہنا تھا کہ اب آنکھ میں آنسو بھی نہیں
پھر شاید عاشق عارضی ناکامی کے بعد گھر لوٹتا ہے۔ محبوبہ کہلا بھیجتی ہے کہ میں ملنے آنا چاہتی ہوں۔ جواب بھی سنیے،
سب کچھ ڈھیر ہے اب مٹی کا
تصویریں، وہ دل کش نقشے
پہچانو تو رو دو گی تم
گھر میں ہوں باہر ہوں گھر سے
اب آؤ تو رکھا کیا ہے
چشمے سارے سوکھ گئے ہیں
یوں چاہو تو آ سکتی ہو
میں نے آنسو پونچھ لیے ہیں
(تقابلی مطالعہ مجاز اب مرے پاس جو آئی ہو تو کیا آئی ہو)
اس کے بعد پھر ایک نئی جد وجہد۔ اب پیسے کا نظام سمجھ میں آنے لگا۔ (’’اب میرااور اس کا آخری معرکہ ہے‘‘ بابا گوریو کے ہیرویوژیں کا آخری مکالمہ۔)
سب ہی جواری، سب ہی لٹیرے، کون کسی سے بازی جیتے
ان جواریوں اور لٹیروں سے مقابلہ کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ باوفا محبوبہ انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ خیال‘‘ پگڈنڈی‘‘ بن جاتا ہے۔ ایک حسینہ درماندہ سی بے بس تنہا دیکھ رہی، ساتھ ہی یہ امید بھی کہ، تاریکی آغاز سحر سے، تاریکی انجام نہیں ہے۔ مگر یہ ’’تاریک سیارہ‘‘ سے پہلے کی منزلیں ہیں۔
’’تاریک سیارہ‘‘ کی ابتدا’’وہ مکان‘‘ سے ہوتی ہے۔ اب شاید محبوبہ کی شادی ہو چکی ہے اور عاشق رات کو مکان کے نیچے کھڑا سنگ و خشت و آہن کی اس تعمیر کو تکے جاتا ہے،
تاکہ وہ پری پیکر
رات کے کسی لمحے
خواب سے اگر چونکے
دیکھ لے مجھے اک بار
یہ وفائے مرگ آثار
میرے دم سے زندہ ہے
’’وفائے مرگ آثار‘‘ کے بعد ’’ترک وفا‘‘ کی منزل ہے،
میں آج وہ عہد توڑت اہوں
یہ رسم وفا بھی چھوڑتا ہوں
’’شکست وفا‘‘ میں محبوبہ ایک بار عاشق کے گھر آتی ہے،
کون ہو؟ بنت مہ و مہر و درخشان نجوم
کس لیے آئی ہو؟ غم خانہ منور کرنے؟
منتظر میں بھی تھا برسوں سے کوئی سیم بدن
نرم مخمل کی طرح، پھول سے ہلکی ہمہ نور
(محبوبہ میں طوائف کا تصور ابھر رہا ہے۔ لہجے کا طنز بھی دیکھنے کی چیز ہے۔)
یوں بڑھے میری طرف جیسے ندی کی لہریں
رات بھر ناچنے والی کی طرح نیند سے چور
(یہ طنز کی انتہا ہے، محبوبہ کو ناچنے والی کہہ دیا۔) آپ نے دیکھا رومانی محبت چاہے کامیاب ہوچاہے ناکام، آخر میں صرف زہر بن جاتی ہے۔ محبت کا انجام نفرت، بلکہ نفرت تو پھر ایک مثبت جذبہ ہے، اس میں کم از کم تحقیر تو نہیں ہوتی۔ پھر اختر الایمان کایہ ’’میں‘‘ تو پھر بھی پر خلوص آدمی ہے، اس لیے برملا محبوبہ کو’’ناچنے والی‘‘ کہہ دیتاہے۔ فیض صاحب کا’’میں‘‘ تو کہتا ہے، اب بھی دل کش ہے تراحسن مگر کیا کیجے۔ اس ملاقات کے بعد بڑی دلچسپ منزل آتی ہے۔ عاشق کو اطلاع ملتی ہے کہ محبوبہ کے بچہ ہوا ہے۔ عاشق کا جواب بھی ملاحظہ کیجیے،
مبارک ہو میں نے سنا ہے کہ تم پھول سی جان کی ماں بنی ہو
مبارک، سنا ہے تمہارا ہر اک زخم اب مندمل ہو گیا ہے
(’’مبارک ہو‘‘ کی تلخی دیکھیے۔ تقابل کے لیے اختر شیرانی کی وہ طنزیہ نظم جس میں انہوں نے عورت کو بچوں کا فحش ترانہ کہا ہے۔)
اختر الایمان کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنی مدت گزر گئی مگر رومانیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہے۔ یہ بقول لارنس کوئی پھول تو ہے نہیں جو مرجھا جائے۔ یہ تو ہیرا ہے جو خود پرستی کی کان سے نکلتا ہے۔ ’’ایک لڑکا’’ کا کردار ’’اختر الایمان‘‘ اسی رومانیت کا ہیرو ہے۔ اب اخترالایمان کی دو شکلیں ہیں۔ باہر والا اختر الایمان، جسے زندگی کے تجربوں نے اسی طرح کچھ سے کچھ بنا دیا، جس طرح ہر آدمی کو بنا دیتی ہے اور ایک اندر والا اختر الایمان جو اس باہر والے اختر الایمان کا ہم زاد ہے اور جنگلوں، شہروں، بازاروں اور گلیوں میں ایک بلا کی طرح اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔
قتیل شفائی کو دیکھیے۔ محبت، پھر محبوبہ کی شادی، ’’ایک موت ایک برات‘‘، اس کے بعد ’’کچھ غم جاناں کچھ غم دوراں‘‘ کی منزل۔ وہی فیض والامعاملہ۔ یعنی اس عشق اور اس عشق والی بات۔ لیکن اس تخصیص کے ساتھ کہ غم جاناں کو جاناں سے بالکل الگ کر لیا۔ اب یہ بالکل ’’روزن‘‘ کے ’’میں‘‘ کی ذاتی ملکیت ہے۔ کیوں کہ جاناں تو غیر کی دلہن بن چکی ہے۔ اس میں ہولناک پہلو یہ ہے کہ اب تک ساحر، جاں نثار، فیض نے بھی محبوبہ پر یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ وہ بک گئی۔ ایک اختر الایمان کے یہاں یہ رنگ جھلکتا ہے مگر ذرا دبا دبا اور قتیل شفائی کے ’’میں‘‘ نے تو صاف اسے ’’رنڈی‘‘ کہا ہے اور سماج کو دلال۔ پھر محبوبہ پر ترس کھانے کی منزل،
خودفروشی کاملال
زندگی کیسے کٹے
اچھا جب محبوبہ ہی خودفروشی کرکے غیر کی آغوش میں پہنچےگی تو عاشق صاحب کیوں صبر کریں۔ ایک رنڈی نہ سہی، یہ دوسری رنڈی کے پاس پہنچیں گے۔ پھر رنڈی سے ہم دردی کازاویہ پیدا کیا گیا ہے، سناہے کہ یہ حسن بازار بھی ایک عورت تھی نیلام ہونے سے پہلے۔ اس میں محبوبہ سے تقابل خود بخود پوشیدہ ہے لیکن اس سب کے باوجود جب کبھی ’’تاروں بھری رات‘‘ آتی ہے تو وہی ایک سوال،
دل میں ہے وہی درد، لبوں پر ہے وہی بات اے تاروں بھری رات
کس طرح بھلائے کوئی گزرے ہوئے لمحاتاے تاروں بھری رات
کسری انسان کی یہ شکل ذرا ہے۔ آدھا عاشق، آدھا رنڈی باز۔ کیا اچھا ہوتا اگر قتیل صاحب ہمیں اس سے کچھ رنڈی بازی ہی کے قصے سنواتے۔ لیکن توجہ آدھے عاشق کے درد کی طرف زیادہ ہے،
اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا
روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی
رومانی سوسائٹی کس طرح آدمی کو توڑتی پھوڑتی ہے، اس کی تمام شکلیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب انہیں عصمت کے تیار کیے ہوئے نقشے سے ملا کر دیکھیے۔ لیکن عصمت نے ہمیں صرف متوسط طبقے کے آدمی کے ٹوٹنے کا نقشہ دکھایا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسری انسان کی یہ شکلیں صرف متوسط طبقے ہی میں بنتی ہیں یا اوپری طبقے میں بھی؟ نچلے طبقے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ کیوں کہ وہاں آدمی ہمیشہ پورا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اوپری طبقے کے آدمی کے بغیر یہ مطالعہ بالکل ناقص ہے۔ ضیا جالندھری کی شاعری کی اہمیت مجھ پر یہیں ظاہر ہوئی۔ ’’سرشام‘‘ میں ہمارے سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ’’سرشام‘‘ کی محبوبہ سے تعارف حاصل کیجیے،
ایک شوخی بھری دوشیزۂ بلور جمال
جس کے ہونٹوں پہ ہے کلیوں کے تبسم کا نکھار
مست آنکھوں سے برستا ہے صبوحی کا خمار
پھول سے جسم پہ ہے شبنمی زر تار لباس
ظاہر ہے کہ ایسی لڑکی سے دیکھنے والے کو صرف جسمانی احساس ہو سکتا ہے،
کروٹیں لیتا ہے دل میں اسے چھونے کا خیال
آنکھیں ملتے ہوئے جاگ اٹھتے ہیں لاکھوں احساس
یہ حسینہ مجھے اکساتی ہوئی آئی ہے
اس ٹکڑے میں ’’چھونے کا خیال‘‘ اور’’اکساتی ہوئی آئی ہے‘‘ خاص ٹکڑے ہیں۔ اب تک ہم نے حسن و عشق کی جتنی شکلیں دیکھی ہیں، یہ ان سے بالکل مختلف شکل ہے۔ نظم کی ساری تفصیلات جسمانی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے،
دل کو برماتا ہے اس شوخ کا بھرپور شباب۔
پرانی شاعری میں عورت اور مرد کی علا متیں پھول اور بھونرا ہیں۔ عورت پھول، مرد بھونرا یا عورت شمع مرد پروانہ۔ متوسط طبقے کی نئی شاعری میں عورت اور مرد کی یہ حیثیتیں نہیں بدلتیں، لیکن ’’سر شام‘‘ میں یہ علامتیں بدل گئیں۔ اب مرد پھول ہے اور عورت تتلی۔ بھونرا بھی ہے مگر پرانی شکل میں نہیں۔ اب وہ رقیب ہے اور رقیب کی روسیاہی کی رعایت سے اپنی اس نئی حیثیت میں جچتا بھی خوب ہے۔ اب تینوں کی یک جائی کا منظر دیکھتے ہیں،
اس پھول کے پاس آئی تھی تتلی
لب مل رہے تھے
یہ ہنس رہا تھا
وہ چومتی تھی
یہ جھولتا تھا
وہ جھومتی تھی
دل کھل رہے تھے
دور ایک بھونرا
شاخوں میں چھپ کر
تتلی کا اس پر کچھ بس نہیں تھا
اب یہ ایک شان دار ڈرائنگ روم کا مکمل نقشہ ہے۔ عاشق محبوبہ اور رقیب سب ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ آخر تتلی بھونرے کی مستقل ’’بھن بھن‘‘ سے تنگ آ جاتی ہے،
اڑنے لگی وہ
افکار سے چور
اڑتی گئی وہ
آفاق سے دور
واپس وہ تتلی آئے نہ آئے
یہ پھول یونہی مرجھانہ جائے
اب کون جانے
تتلی واپس نہیں آئی۔ پھول انتظار کرتا رہتا ہے۔ آنسوؤں کی شبنم اسے کچھ دن تازہ رکھتی ہے مگر تابہ کے۔ رفتہ رفتہ شبنم خشک ہونے لگتی ہے۔ نتیجہ وہی بے حسی۔ طبقہ کوئی بھی ہو، رومانیت تو اپنی منزلوں سے گزرےگی،
یہ ٹھٹھرتی تیرگی، بے جان یخ بستہ زمیں
اور اس پر راکھ، ٹھنڈی راکھ کے اس ڈھیر میں
کوئی چنگاری، ذراسی، آنچ کا سامان نہیں
پھول جانتا ہے کہ شبنم نہ آئےگی تو وہ خشک ہو جائےگا، اس لیے ’’سرشام‘‘ کی تین چوتھائی نظموں کا موضوع ’’آنسو‘‘ ہے۔ کبھی یہ کہ آنسوؤں نے جل تھل بھر دیے۔ کبھی یہ کہ آنسو بھی نہیں رہے۔ (غزل میں قافیہ ردیف ہے چھم چھم برسا)،
مگر میں کب سے ترس رہا ہوں
کہ میری پتھرائی خشک آنکھوں سے بھی کچھ آنسو
ابھرتی لہروں کی طرح ابھریں
اور ان کی حرکت میں ڈھل کے بہہ جائے میرے سینے کا درد سنگیں
محبوبہ سے ملاقات کا ایک منظر دیکھیے،
وہ اک ہجوم طرب، وہ نشاط نغمہ ونور
شریر لڑکیاں، رنگین تتلیاں بے تاب
لبوں پہ گل کدۂ گفتگو کھلائے ہوئے
وہ قہقہے وہ مسرت کی نقرئی جھنکار
تم آئیں، ہنستی ہوئی آئیں، برق کی مانند
مرے قریب سے کتنی قریب سے گزریں
اچھا’’سرشام‘‘ کی محبوبہ تو متعین ہو گئی۔ لیکن عاشق صاحب سے ابھی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی نظم میں انہیں بھی دیکھیے،
میں اپنے گوشۂ کم تاب میں ہجوم سے دور
اداس نظروں میں مدھم دیے جلائے ہوئے
تتلی کے مقابلے پر اس پھول کو دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے۔ یہ پھول ڈرائنگ روم میں کیسے کھلا (کیا یہ متوسط طبقے سے اوپر آیا ہے) اس عاشق کو محبوبہ کے قہقہے سن کر چوٹ لگتی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسی قہقہے نے اسے تتلی بنا دیا ہے۔ وہ اسے تتلی سے محبوبہ بنانا چاہتا ہے اس لیے اس کا تجزیہ کرتا ہے،
مگر کبھی کبھی جس طرح کوئی سایہ سا
کہ اس جمال و مسرت کی تہ میں پنہاں ہے
وہ روح تیرہ جسے اک کرن نصیب نہیں
محبت کے لیے ضروری ہے کہ تتلی اس طرح قہقہے لگانا چھوڑ دے،
ہنسو اور اتنا ہنسوت م برس پڑیں آنکھیں
پھر ان سلگتے ہوئے آنسوؤں میں بہہ جائے
وہ درد اور وہ دوری جو قہقہوں میں ہے
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ’’سرشام‘‘ کا عاشق اسے تتلی سے محبوبہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے،
ہم ایک تھے، ایک تھے ہم دونوں
ہم ایک ہی دکھ کے مارے تھے
دونوں کے دھڑکتے سینوں میں
صرف ایک ہی درد سلگتا ہے
لیکن یہ تو ڈرائنگ روم والی دنیا ہے۔ محبوبہ کو دوسری تتلیاں اپنے سے مختلف کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ نتیجہ:
نہیں نہیں آپ پیار کی کوئی بات مجھ سے نہ کیجیےگا
وگرنہ لوگوں کی ناگنوں سی سیہ زبانیں مجھے ڈسیں گی
اس کے بعد عشق کی کئی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ جدائی، انتظار، بے حسی، ادراک دم ایک نیا تجربہ، یہ لذت جسم ہے عجب شے۔ ایک دم امید بندھتی ہے کہ ’’سرشام‘‘ کا’’میں‘‘ ہمیں اس لذت کی داستانیں سنائےگا اور ایک بہت خوب صورت نظم’’وصال‘‘ پڑھنے کو ملتی بھی ہے۔ مگر خدا جانے اس تجربے میں کیا کھوٹ ملا ہوا ہے کہ اس عاشق کی نظر بھی بار بار کسی اور طرف لوٹ جاتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وصال محبوبہ سے نہیں محبوبہ کی بہن سے ہوا ہے،
میں بھی سمجھی تھی اسے دل سے قریب
میری معصوم بہن، میری رقیب
اس عاشق نے جسم تو دریافت کر لیا۔۔۔ نچلا دھڑ، لیکن اوپر کا دھڑ اب بھی اسی محبوبہ کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے۔ اب نچلا دھڑ اپنا کام کرتا رہےگا، اوپر کا دھڑ اپنا کام۔ یہاں تک کہ آنسو خشک ہو جائیں گے اور پوری شاعری صرف آنسوؤں کے خشک ہونے کا ماتم بن جائےگی۔ ’’سرشام‘‘ میں تتلی اور پھول کے اس عاشق کی کہانی کے بعض مرحلے بڑی نزاکتوں کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ مگر ہم اس وقت شاعری کے بجائے رومانیت کی شکلیں دیکھ رہے، اس لیے اس کا ذکر پھر کسی اور وقت۔ آئیے اب ہم اپنے نکالے ہوئے نتائج پر بہ حیثیت مجموعی غور کریں،
(۱) جس سوسائٹی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی ماہیت کچھ ایسی ہے کہ وہ محبت کو عاشق و محبوب کے حسب منشا کامیاب نہیں ہونے دیتی۔
(۲) محبت کی ناکامی کے بعد عاشق اور محبوب کے لیے صرف دو راستے رہ جاتے ہیں۔ یا تو دونوں خودکشی کر لیں اور محبت کاح ق ادا کر جائیں۔ یازندہ رہیں اور اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق شادیاں کر لیں۔ اس دوسری صورت میں بھی دو حصے ہیں۔ (الف) شادی کو اپنے پورے وجود کا تقاضا سمجھیں یا (ب) شادی کو صرف جسمانی ضرورت کا نتیجہ قرار دیں اور روح یا شعور کو اس تجربے سے ملوث نہ ہونے دیں۔ یہ مؤخرالذکر طریقہ رومانی ہے۔
(۳) رومانی طریقے کی جتنی شکلیں ہم نے اب تک دیکھیں ہیں۔ ان سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں،
مرد اورعورت کی محبت کی وہ صورت جس میں جنس کا خیال بھی شعور میں نہ آئے، (اختر شیرانی)، ایک تخیلی چیز ہے۔ عنفوان شباب میں لڑکے اور لڑکیاں اپنے جسمانی وجود کو گندہ سمجھ کر اسے اپنے شعور میں جگہ نہیں دیتیں۔ صحت مند آدمی کی زندگی میں یہ ایک عارضی وقفہ ہوتا ہے۔ اس میں مریضانہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ اپنے فطری وقت پر ختم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی ذہنی عمر اس کی جسمانی عمر کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مریضانہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر ذہنی طور پر عنفوان شباب کے دور سے نہیں گزرتے۔ ان کے وجود کی جسمانی ضروریات، ذہنی ضروریات سے الگ ہو جاتی ہیں اور وہ جسمانی ضروریات کو ہمیشہ ناپاک تصور کرتے رہتے ہیں۔ سوسائٹی کے انتشار کا معتدبہ حصہ انہیں غیرصحت مند افراد کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔
اس حقیقت کا ایک دوسرارخ بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابتدا میں صحت مند ہوتے ہیں۔ یعنی محبت کی جسمانی اور روحانی وحدت کا شعور رکھتے ہیں مگر کسی خاص سبب سے آگے چل کر ذہن اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً محبوبہ سے جنسی قربت کاحصول نہ کرسکنا (ساحر، جاں نثار، اختر الایمان، قتیل شفائی، ضیا جالندھری) اس کے بعد حقیقی فطری محبت، اپنی اصلی حیثیت گم کر دیتی ہے۔ اور اس کی جگہ اس کی ایک مسخ صورت جنم لیتی ہے۔ فرد محبوبہ سے جنسی قربت حاصل نہ کر سکنے کو اپنی ذاتی شکست سمجھتا ہے اور شکست کو ذہنی طور پر قبول نہیں کرنا چاہتا۔ محبت کی مسخ شدہ صورت اسی شکست خوردگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ صرف خودپرستی کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ یہاں عنفوان شباب والی کیفیت پھر لوٹ آتی ہے۔ فرد اپنی شکست خوردگی کو ایک طرح کی مصنوعی عظمت میں بدل دیتا ہے۔
اس نام نہاد عظمت کی کئی شکلیں ہیں۔ فرد پہلے تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو میں اس محبت کو مرنے نہیں دوں گا (رومانی وفا) لیکن محبوب سے مستقل جدائی کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ جذبہ اپنی پہلی صورت میں محسوس نہ ہو۔ لیکن چوں کہ فرد اس میں اپنی سبکی تصور کرتا ہے، اس لیے اس جھوٹے جذبے کو اپنے اوپر طاری کرنے کی مستقل کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس نفسیاتی کش مکش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر قسم کے احساس سے عاری ہو جاتا ہے (رومانی بے حسی) اس بے حسی سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ فرد اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے لیکن سب میں اہتمام یہی مدنظر رہتا ہے کہ شکست خوردگی کے احساس کوعظمت میں ڈھالا جائے اوراسے محبت سے منسوب کیا جائے۔
یہ کبھی دنیا کے تمام انسانوں کے دکھ بانٹ لینے کی خواہش بن جاتی ہے (رومانی انسانی پرستی) کبھی معاشرے کے نظام کو یکسر بدل دینے کے خواب دیکھتی ہے (رومانی انقلابیت) کبھی خود کو فنا کرکے محبوب کی شان دوبالا کرنے کا ارادہ باندھتی ہے (رومانی ایثار) اور جب ان سے کچھ نہیں ہو پاتا تو اپنا مداواان چیزوں میں ڈھونڈتی ہے جنہیں کسری سوسائٹی کا سب سے روشن پہلو کہا جاتا ہے۔ عہدہ، دولت، مادی ترقی۔ مادی ترقی کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر۔ جب یہ عمل فرد کے بجائے قوم اختیار کرتی ہے تو بندوق لے کر وحشی اقوام کو تہذیب اور جمہوریت سکھانے نکلتی ہے۔ اس سفر کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک براعظم سے دوسرے بر اعظم تک۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا تک۔
اب چاند کا سفر کسری آدمی کا عظیم ترین کارنامہ بن جاتا ہے۔ اس سے نئی تہذیبی قدریں پیدا ہوتی ہیں۔ فرد کی زندگی میں بات کار، عہدہ، بینک بیلنس تک محدود رہتی ہے مگر یہ صرف بڑے پیمانے اور چھوٹے پیمانے کا فرق ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسخ شدہ آدمی کے ان شاندار کارناموں سے اصلی آدمی مطمئن نہیں ہوتا۔ اب وہ بھی انتقام لےگا۔
کسری آدمی جب اپنے دفتر سے چمچماتی ہوئی کار میں بیٹھ کر کوٹھی۔۔۔ اور وہ جو اس کا ہم شکل، اس کا آئیڈیل اور اس کی عظمت کی انتہا ہے، اپنے شان دار خلائی سفر سے دنیا میں لوٹےگا تو روٹی مٹی بن جائےگی اور پانی زہر۔ اور گھر کے بیوی بچے تیسری جنگ عظیم کے خوف سے سوتے میں کانپ کانپ اٹھیں گے اور برٹرینڈرسل صاحب فرمائیں گے کہ یورپ چند ہی برسوں میں ختم ہوجائےگا۔ شاید یورپ کے ساتھ دنیا بھی (تازہ اطلاع ہے کہ رسل صاحب اس جرم میں سزا پا گئے۔) آخر میں یہ سب عناصر مل کر اکتاہٹ اور بےحسی کو ایک دوسرے سے ضرب دے کر بڑھاتے بڑھاتے ایک ہمہ گیر بے کیفی میں ڈھال دیں گے۔ اردو شاعری کاپہلارومانی غالب آگے ہی کہہ گیا ہے،
بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق
بے بسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دیں
اب ہم ٹھیک ۱۹۶۱ میں ہیں اوراپنی سوسائٹی اور شاعری کا جائزہ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں۔ سوسائٹی کا جائزہ اپنے سے بہتر لوگوں کے لیے چھوڑ کر میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔
اردو کی نئی نظم اور اس کی حقیقی قدر وقیمت اس سے پہلے طول طویل مثالوں کے ذریعے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اس شاعری کا اولین دور وہ ہے جب شاعر عنفوان شباب کے تجربات کو ہلکے پھلکے جذباتی انداز میں بیان کرتا ہے۔ یعنی اٹھارہ برس کی عمر والوں کی شاعری۔ یہ اس شاعری کا بہترین دور ہے۔ نئے نظم نگاروں کے کم و بیش ساٹھ ستر مجموعے اس وقت میرے سامنے رکھے ہیں اور ان میں سب کے دیباچوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ اردو شاعری کاتابناک مستقبل انہیں لوگوں سے وابستہ ہے۔ یہ پیش گوئی یقیناً بڑی شان دار ہے مگر اس کا حقیقی انجام ہم سب کے سامنے ہے۔ انجام کے ذاتی اور سماجی اسباب پر میں تفصیل بحث کر چکا ہوں۔ اب صرف نتائج کو دیکھتے جائیے۔
چوں کہ یہ شعراعنفوان شباب کی منزل سے نکل کر زندگی کے حقیقی تجربات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ان میں سے بیشتر کا انجام یہ ہوا کہ ان کی شاعری کے سوتے ہی خشک ہو گئے اور وہ اردو شاعری کے مستقبل کو تابناک بنانے کی کوشش چھوڑ کر اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی مساعی جمیلہ میں مصروف ہو گئے۔ چلیے چھٹی ہوئی۔ خدا مغفرت کرے۔ اس کے بعد نمبر ان لوگوں کا آتا ہے جو پبلشر کے تقاضوں کے باعث یا دوستوں کی شرماحضوری میں یا کسی اور معقول کام کے نہ ملنے کے باعث شاعری چھوڑنے کا کام نہ کر سکے۔ انہوں نے دو راستے اختیار کیے۔ کچھ حضرات نے یہ راستہ اختیار کیا کہ وہ اپنے مسخ شدہ تجربات ہی کو اس طرح بن اسنوار کر پیش کریں کہ وہ حسین معلوم ہونے لگیں۔ یہ شاعری بیشتر اپنے اوپر ترس کھانے کی مریضانہ کیفیت کا شکار ہے اور روز بہ روز اس کی آواز رقیق سے رقیق تر ہو کر صرف’’روں روں‘‘ میں تحلیل ہوتی جا رہی ہے۔
جن لوگوں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا، وہ اپنے پورے وجود کو چھوڑ کرصرف کسی خیال یا نظریے کے ہوکر رہ گئے۔ لیکن سوسائٹی کی موجودہ حالت میں جو ہر آئیڈیل کو جھٹلا چکی ہے، وہ بھی اپنے کام کو جاری نہ رکھ سکے اور اپنے پہلے ساتھیوں سے آملے۔ اب صرف ایک جذباتی ملغوبہ ہمارے سامنے ہے، یا یوں کہیے کہ اگر بودلیئر کے بجائے بودلیئر کی صلیب پر لٹکی ہوئی لاش شاعری کر سکتی تو وہ اسی قسم کی ہوتی۔ اس شاعری کا محرک صرف ایک ہے۔ سڑی ہوئی لاش کی یہ خواہش کہ وہ حسین نظر آئے۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ کو اس لاش کے سڑنے کی بو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟
مأخذ:
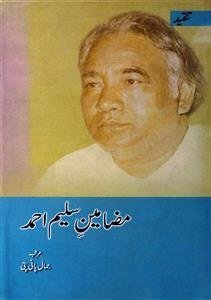
مضامین سلیم احمد (Pg. 24)
- مصنف: سلیم احمد
-
- ناشر: اکیڈمی بازیافت، کراچی
- سن اشاعت: 2009
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.

