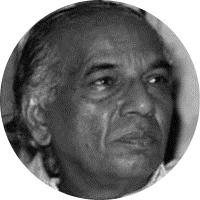مسعود حسن رضوی ادیب
مسعود صاحب میرے استاد تھے، میرے بزرگوں کے دوست تھے، بعض ادبی امور میں رہنما تھے، پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میں ان سے زیادہ ان کے بھائی آفاق کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات مسعود صاحب ہی کے ذریعے سے ہوئی۔ دراصل مسعود صاحب کو بہت قریب سے جاننا مشکل بھی تھا۔ وہ کم آمیز ہونے کی حدتک گوشہ نشین تھے۔ وقت کا کافی حصہ بہت بڑا حصہ، مطالعہ و تحقیق میں صرف کردیتے تھے اور گھروالوں کو بھی ان مشاغل میں داخل اور حارج نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ‘‘قطب از جانمی جنبد’’ قسم کے لوگوں میں رہے ہوں۔ ان کا اپنا ذاتی تانگہ تھا اس پر سوار ہوکر وہ یونیورسٹی بھی جاتے اور دوستوں کے یہاں بھی، لیکن یہ آمد و رفت نہ بہت زیادہ تھی نہ بہت کم، کم آمیزی کے باوجود ان کے دوست بہت تھے اور کئی طبقوں میں تھے۔ پھر قدیم و جدید شاگردوں کا ایک حلقہ تھا لیکن گھروالے کیا دوست، کیا شاگرد، سب کے فاصلے اور قربتیں متعین تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے کو لیے دئے رہتے اور کسی کو حدود سے تجاوز نہ کرنے دیتے تھے۔ وضعداری، روایت اور شرافتِ نفس نے جو قیود عائد کردیے تھے ان سے وہ خود بھی منحرف تھے۔
وہ بڑے رکھ رکھاؤ کے انسان تھے اور رکھ رکھاؤ کو بے ترتیبی، بے نظمی ،بے احتیاطی، حفظ مراتب سے بےپروائی یا افراط و تفریط سے لگاؤ نہیں۔ ان کی زندگی ایک نظم، ایک ترتیب، ایک توازن کا نام تھی اور ان کا کمال یہ تھا کہ انھوں نے اسی برس سے بھی زیادہ طویل زندگی میں اس ربط و توازن کو بگڑنے نہ دیا۔ حفظ مراتب کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی ملاقاتی روزمرّہ کے کاموں سے آتا تو وہ اس سے اپنے وسیع مکان کے برآمدے ہی میں مل لیتے۔ وہاں ایک ہشت پہل یا گول (مجھے ٹھیک سے یاد نہیں) میز پر پڑی رہتی تھی جس کے گرد دوتین کرسیاں ہوتیں، یہ گویا ان کا ایوانِ عام تھا۔ یہاں سرسری سماعت اور سرسری فیصلے نہیں ہوتے بلکہ حسب مرتبہ تفصیلی گفتگو ہوتی۔ ہر آنے والے کی حسب مرتبہ تواضع ہوتی۔ فرمائش کے بغیر ہی چاندی کے نقشی خاصدان میں فوراً پان کی گلوریاں پیش ہوتیں، چائے کا وقت ہوتا تو چائے بھی آتی یا گرمیوں کے زمانے میں ٹھنڈا شربت۔ اگر کسی سے بے تکلفی ہوتی تو بے وقت بھی چائے منگالی جاتی۔ یہ تواضع ہر کس و ناکس پر ضائع نہ کی جاتی۔ آخر انھیں یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ وہ اپنے نپے تلے وقت میں سے کسی کو کتنا دیں۔ معمولی کام والے اپنا کام کرکے بے تاخیر واپس جاتے لیکن اگر کوئی ایسی ہستی ہوتی جس سے علمی یا ادبی گفتگو کی کسی سطح پر گنجائش ہوتی تو اس کے لیے وقت نکل آتا۔ حد یہ ہے کہ ادبی کاموں سے دلچسپی رکھنے والے شاگردوں کی پذیرائی بھی اچھی طرح ہوتی۔
میں نے مسعودصاحب کو سب سے پہلے ۱۹۳۱ء میں علی عباس حسینی کے یہاں دیکھا تھا۔ اس وقت میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا مگر لکھنے پڑھنے کا چسکا اس وقت بھی تھا اور دو برس پہلے ہی میرے مضامین اور اشعار اخبارات و رسائل میں شائع ہونے لگے تھے۔ اس وقت مسعود صاحب پر اس مصرعے کا اطلاق نہیں ہوسکتا تھا کہ ‘‘چہل سال عمر عزیزت گزشت’’ اڑتیس برس کا سن عین جوانی کہیے۔ اس کے بعد وہ ادھیڑ ہوئے، ریڈر سے پروفیسر ہوگئے۔ پنشن پاگئے۔ یہاں تک کہ ہم سے جدا بھی ہوگئے۔ لیکن ۱۹۷۵ء میں انتقال کے وقت تک ان میں تبدیلی نہیں آنے پائی۔ وہی رکھ رکھاؤ، وہی نوک پلک باقی رہی۔ ان کے دوستوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا لیکن جو پہلے کے دوست تھے وہ چھوٹے بھی نہیں۔ وہ ‘‘وفاداری بشرط استواری’’ کے قائل تھے۔
میں پڑھنے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا کہ مسعود صاحب مردم بیزار یا مغرور تھے۔ وہ یار باش نہیں تھے لیکن ان کے دوستوں کا حلقہ کافی وسیع تھا۔ اس میں لکھنؤ کے وہ نواب بھی تھے جو ‘‘چنیا بیگم’’ کے عاشق اور ‘‘پالی’’ کے مردِ میدان تھے۔ وہ بانکے بھی تھے جو قدیم فنون حرب و ضرب میں طاق تھے، وہ داستان گو بھی تھے جن کی لسانی نیند اڑادیتی تھی اور وہ خطیب بھی تھے جو سننے والوں کو محو حیرت کردیتے تھے۔ ان میں وہ مرقع ہائے عبرت بھی تھے جو سابق خاندانِ شاہی کے چشم و چراغ یا عملی و ادبی خانوادوں کی یادگار تھے۔ اخباروں کے مدیر اور اسکولوں کالجوں کےاستاد، مجتہد، طبیب اور ڈاکٹر مغنی اور شاعر، افسانہ نویس اور نقد نگار، ترجمے کے ماہر اور نثار، مرثیہ خواں اور مرثیہ گو، مزاح نویس اور نقدنگار، سماجی کارکن اور سیاست کے علمبردار، خطّاط اور مصور، تاجر اور سائنسداں بھی تھے۔ اس مختلف النوع اور رنگارنگ مجمع میں ہر جگہ مسعود صاحب کی مخصوص جگہ تھی اور مسعود صاحب کے ہاں ان کی مخصوص پذیرائی۔ ان میں سے کسی مجمع میں بھی وہ نہ تو اس طرح گھل مل جاتے کہ اس کا تخمیری حصہ بن جائیں اور نہ بیگانہ وار تماشائی مثال، کسی نامعلوم گوشے ہی میں بیٹھے رہتے۔ ہرجگہ اپنی سنجیدہ انفرادیت کو سنبھالے رہتے لیکن دوسروں پر انفرادیت کو وارد نہ کرتے۔ اہل علم اور بزرگوں کا خود بھی احترام کرتے اور برابر والوں اور دوستوں کو بھی حد سے بڑھنے کی اجازت نہ دیتے۔ اپنے چھوٹوں کی بات بھی خموشی سے سنتے۔ لطائف و ظرائف کا سلسلہ شروع ہوتا تو اپنی جانب سے بھی کچھ سنجیدہ اضافے کرتے۔ ادبی اور علمی مباحثوں میں اپنی بات پورے زور و شور سے کہتے۔ دوسروں کی سنتے، جواب الجواب دیتے لیکن لوگ جانتے تھے کہ مسعود صاحب نہ اس حد کے آگے جائیں گے نہ کسی اور کو جانے دیں گے۔
میں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ لیکن میں شاگرد بعد میں بنا اور نیازمند پہلے۔ مسعود صاحب کو میں نے اسکول کے ابتدائی درجات ہی سے پڑھنا شروع کردیا تھا اور اس سے پہلے شناسائی رسائل کے ذریعے سے ہوئی۔ زیارت بھی اسی زمانے میں حسینی صاحب کے یہاں ہوئی۔ اس زمانے میں علی عباس حسینی جو دہلی کالج میں تاریخ پڑھاتے اور رومانی افسانے لکھتے تھے۔ ان کے قریب ترین ادبی دوستوں میں اختر علی تلہری، خواجہ اطہر حسین اور مسعود صاحب ہی تھے۔ یہ لوگ ان کے یہاں اکثر آتے۔ خواجہ صاحب اور تلہری صاحب تقریباً روزانہ اور مسعود صاحب کبھی کبھی۔ اس وقت تک حسینی صاحب سے میری صرف ایک دوری قرابت تھی۔ وہ سید اعظم حسین اعظم (سابق مدیر سرفراز) اور شمیم کرہانی کے حقیقی ماموں تھے اور اعظم حسین و شمیم میرے ماموں کے یک جدّی بھتیجے تھے۔ غالباً تین پشت اوپر یہ دونوں شاخیں ایک نقطے پر مل جاتی تھیں۔ میں جب کبھی لکھنؤ جاتا تو اعظم بھائی سے ملنے ضرور جاتا۔ وہ حسینی کے ساتھ ہی رہتے تھے اور سہ روزہ ‘‘سرفراز‘‘ جو بعد میں روزانہ ہوگیا تھا اور اب صرف ہفتہ وار بھی نہیں رہ گیا، کے نائب مدیر بھی تھے اور ایک علمی اور ادبی رسالہ ‘‘ادب’’ بھی نکالتے تھے۔ ادب سے حسینی، تلہری اور خواجہ اطہر (جنھوں نے ایک زمانہ میں رند کے فرضی نام سے بہت اچھے مزاحیہ مضامین لکھے تھے) خاص وابستگی رکھتے تھے۔ یہ تینوں سرکاری ملازم تھے اور کسی اخبار یا رسالے سے وابستگی سرکاری قواعد ملازمت کے خلاف تھی۔ لیکن واقفانِ کار کا کہنا یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات اس کے بانیوں میں تھے اور غالباً مسعود صاحب کو بھی دامے اور قلمے ان کے ساتھ تھے۔ دوستی کے علاوہ ‘‘ادب’’ کے ادارتی امور میں مشورت بھی مسعود صاحب حسینی صاحب کے یہاں کھینچ لاتی تیف۔ اس کے علاوہ اعظم ،آرزو لکھنوی کے شاگرد تھے، اور بعض خانگی مجبوریوں کی بناپر آرزو کو اعظم حسینی صاحب کے مکان ہی پر بلالاتے تھے۔ ان کی زباندانی اور شاعری دونوں ہی جاذب توجہ تھیں۔ ان کی وجہ سے بھی مسعود صاحب اکثر آنے لگے تھے۔ یوں بھی ان اصحاب اربعہ (مسعود تلہری، حسینی اور اطہر) میں بڑی ذہنی یگانگت تھی۔ جب یہ سب جمع ہوتے تو اِدھر ادھر کی باتیں ہوتیں، شاعری ہوتی، افسانے اور مضامین سنائے جاتے، نقد و تبصرہ ہوتا، ہلکی اور قومی مسائل پر تبادلہ خیال ہوتا۔ ان میں، میں بھی دخل اور معقولات کرتا اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنی سی کہتا رہتا۔ پھر ۱۹۳۵ء سے مستقل طور پر لکھنؤ آگیا۔ اب یہ ملاقاتیں جلد جلد ہونے لگیں۔ ان کی خدمت میں یہ چند سال اس نیاز مندی کے ساتھ گزرے کہ میں ان کی سخن شناشی اور دیدہ وری کا قائل ہوگیا اور اپنے کو ان کے خاصا قریب پانے لگا۔ لیکن یاد دلاتا چلوں کہ یہ قربت بھی دوری کی قربت تھی، میں نے اسی زمانے میں مسعود صاحب کی ‘‘ہماری شاعری’’ پڑھی۔ یہ کتاب دراصل نقد ادب میں اس مغرب زدگی کے خلاف صدائے احتجاج تھی جو بیسویں صدی کے پہلے ربع میں اردو شاعری کے اکتسابات کے کلی انکار کی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ مسعود صاحب نے اردو شاعری کے بہت سے اسرار و عوارض کے چہرے سے نقاب اٹھادی۔
مسعود صاحب کے دوستوںمیں چند حضرات اور تھے۔ شیخ ممتاز حسین عثمانی (ایڈیٹر ‘‘اودھ پنچ’’) حکیم صاحب عالم (مالک دواخانہ ‘‘مورن الادویہ’’) مرزا محمد عسکری (مصنف ‘‘من کیستم’’ اور مترجم ‘‘تاریخ ادب اردو’’ مؤلفہ رام بابو سکسینہ’’) سید علی نقی صفی اور مولانا ظفرالملک (مدیر ‘‘الناظر’’) یہ سب کے سب لکھنؤ کی ادبی انجمنوں کے ستون تھے۔ اور خدا انھیں بخشے، بڑے ثقہ اور رتبہ شناس لوگ تھے۔ شیخ ممتاز حسین عثمانی اس دور کے ادبی ماحول میں قطب الاقطاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے یہاں جانے والے بہت تھے لیکن وہ شاید ہی کسی کے یہاں جاتے ہوں، البتہ کھرے دوست اور کھلے دل سے دشمن تھے۔ وہ مسعود صاحب کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ایک زمانے میں مسعود صاحب کے ایک ہم وطن، بیخود موہانی نے ‘ہماری شاعری’ کے خلاف رسالہ بازی شروع کی ،پہلے کی چھوٹے چھوٹے رسالے مثلاً ‘‘آئینہ تحقیق’’ لکھے اور بعد میں ان سب کو یکجا کرکے ‘‘گنجینۂ تحقیق’’ کے نام سے تحقیقی کتاب کی صورت میں شائع کرادیا۔ اس پر ممتاز حسین عثمانی نے ‘‘اودھ پنچ’’ میں ‘‘گنجۂ ناتحقیق’’ کے نام سے وہ لے دے کی۔ بیچارے بیخود تلملا اٹھے۔
حکیم صاحب عام لکھنؤ کے شرفاء میں تھے۔ بہت اچھے طبیب، معقول شاعر اور اچھے ادب نواز دوست تھے ۔نخاس میں ان کا مطب معدن الادویہ تھا۔ کبھی کبھار مطب میں ملاقات ہوجاتی، کبھی ان کے بے حد بے تکلف اور خوش مزا دعوتوں میں یکجائی ہوجاتی اور کبھی کبھی ان مقاصدوں میں ان ملاقاتوں کے دوران کبھی آپس میں مسکراہٹوں اور لطیفوں کا تبادلہ ہوتا اور کبھی علمی، ادبی یا سیاسی مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات مگر بہت نپا تُلا اور مختصر۔ حکیم صاحب کی طبابت سے بھی کبھی استفادہ کرتے لیکن غالباً کشش کا ایک سبب یہ تھا کہ حکیم صاحب کا خاندان اودھ کے شاہی طبیبوں کا خاندان تھا۔
علامہ صفی لکھنؤ سےملاقاتیں خالص ادبی نوعیت کی ہوتیں، کبھی مشاعروں اور مقاصدوں میں اور کبھی شیعہ کانفرنس کے اجلاسوں میں یہ کانفرنس ایک سماجی ادارہ تھا۔ اخبار ‘سرفراز’ اور ‘‘شیعہ یتیم خانہ’’ دو ادارے اس کے ماتحت چلتے تھے۔ کئی اصلاحی تحریکیں اس کانفرنس نے چلائیں اس لیے علماء سے اس کا ٹکراؤ ہوا اور وہ اس سے بالکل کنارہ کش ہوگئے۔ خیال یہ تھا کہ علماء کی علیحدگی کے بعد کانفرنس ختم ہوجائے گی۔ اس عالم میں جن لوگوں نے اس کو سنبھالا ان میں یہی ارباب اربعہ تھے۔
مسعود صاحب بڑے ہی مرنجان، مرنج قسم کے انسان تھے وہ اچھے مسلمان اوراچھے شیعہ تھے لیکن ان کو تعصب اور تنگ نظری کی ہوا نہیں لگی تھی۔ وہ ایک بار ایسا بھی ہوا ہے کہ انھوں نے کسی مسلمان کو ہندو کے مقابلے میں اور شیعہ کو سنی کے بارے میں اس کی غلطیوں پر ٹوک دیا ہے۔ یونیورسٹی کی سیاست میں ایک بار ڈاکٹر بیربل ساہنی اور ڈاکٹر ولی الحق ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوگئے۔ مسعود صاحب نے ڈاکٹر ساہنی کا ساتھ نہ چھوڑا۔
مذہبی ہونے کی وجہ سے انھوں نے ‘‘انگارے’’ کی اشاعت پر بڑی رضامندی کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے مصنفین میں سجاد ظہیران کی یونیورسٹی کے طالب علم رہ چکے تھے اور احمد علی ان کے رفیق تھے۔ ان سے بھی اور ڈاکٹر رشید جہاں سے بھی ان کےتعلقات کبھی ناخوشگوار نہ ہوئے۔ اختلاف خیال کا احترام کرنا اور اپنے خیال کو ترک کیے بغیر دوسرے کی آزادی خیال کو حق بجانب سمجھنا علمی رواداری کا خاصہ ہے اور یہ خصوصیت مسعود صاحب نے اپنالی تھی۔
مسعود صاحب کی جوانی تک ایسے کئی اصحاب تھے جو اپنے ناموں کے ساتھ ‘‘ثم لکھنوی’’ لکھا کرتے تھے۔ مثلاً دہلوی ثم لکھنوی، مطلب یہ تھا کہ پہلے کیںو اور جگہ کے رہنے والے تھے بعد میں سکونت ترک کردی اور لکھنوی ہوگئے اس میں ایک طرف تو ان کے اس جذب و خلوص و فخر کا اظہار ہوتا تھا جو اپنے وطن کے لیے ان کے دلوں میں گھر کئے ہوئے تھا۔ اور دوسری طرف لکھنویت کے فخر کا بھی مظاہرہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ جو زیادہ شدید لہجہ تھے وہ کہتے کہ یہ اصل میں ثم اظہار برأت کے طور پر لکھتے ہیں کہ ہمیں خالص لکھنوی نہ سمجھ لیا جائے۔ مسعود صاحب بھی ثم لکھنوی تھے یہ کیوں کہ ان کا اصلی وطن انّاؤ کے پاس ایک قصبہ نیوتنی تھا۔ اناؤاور لکھنؤ میں کچھ فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ غالباً پچیس تیس میل کا فاصلہ ہوگا۔ اس کا شمار مضافات لکھنؤ میں ہی کرنا چاہیے۔ لیکن کانپور سے قربت زیادہ ہونے کی وجہ سے ذہنوں میں اس کا تصور لکھنؤ سے قربت کا کم ہی ہے۔ مسعود صاحب کو لکھنؤ سے عشق تھا۔ یہ اسی عشق کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے یہاں مکان بنالیا اور یہیں رہ پڑے اس معنی میں وہ ‘ثم لکھنوی’ ہوگئے۔ لیکن مسعود صاحب کو لکھنؤ سے جو گہری وابستگی تھی اس کے پیش نظر انھیں ‘ثم لکھنوی’ والی صف میں شامل کرنا زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ مرنے سے پہلے وہ سوفیصد لکھنوی ہوچکے تھے۔
وہ لکھنؤ کے لیے‘‘تازہ واردان بساط’’ کی حیثیت رکھتے تھے لیکن لکھنؤ کی محبت میں وہ لکھنو کے قدیم باشندوں سے بھی آگے تھے۔ انھیں لکھنؤ کے ذرّے ذرّے سے محبت تھی۔ انیس اور واجد علی شاہ ان کی زندگی بھر کی ادبی اور تخلیقی کاوشوں کا مرکز رہے۔ ان کے علاوہ لکھنؤ ان پر فدا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ فدائے لکھنؤ ضرور تھے۔ یہ محبت ادبی اور ثقافتی زیادہ تھی اور علاقائی کم۔ یعنی انھیں لکھنوی ثقافت اور لکھنؤ کے مرکز ادب سے دلچسپی تھی۔ انھوں نے یہاں کی مثنویاں، یہاں کے قصیدے ،یہاں کے واسوخت ،یہاں کی داستانیں سب پڑھ ڈالی تھیں، تاریخ اودھ پر بھی ان کی اچھی نظر تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ واجد علی شاہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، انگریزوں نے حکومت چھیننے کی خاطر سے بہت سی روایتیں گڑھیں اور گڑھوائیں۔ محل سراؤں کا ماحول اور رنگ رلیاں بھی ضرور تھی، لیکن یہ سب مدتوں سے لازمۂ ریاست بن گئی تھیں ۔ واجد علی شاہ کو رقص و سرود سے دلچسپی ضرور تھی لیکن یہ دلچسپی فنی تھی۔ اس کو لہو و لعب سے وابستہ کرنا درست نہیں۔ یہ اور اس قسم کی باتیں ان کی صحبت میں اکثر سننے کو ملتیں اور وہ سب کے لیے شہادت پاس رکھتے تھے۔ انھوں نے واجد علی شاہ، اودھ اور لکھنؤ پر اردو، فارسی، انگریزی میں بہت سا مواد جمع کرلیا تھا۔ وہ لکھنا بھی چاہتے تھے لیکن ظالم وقت نے فرصت نہ دی۔
مسعود صاحب کوئی تراسی برس پہلے خاص محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ ان کو مرثیوں سے جو خاص شغف تھا شاید اس میں ادبی لگاؤ کے علاوہ تاریخ پیدائش کو بھی دخل رہا ہو، مسعود صاحب خود نہ تو مرثیہ گو تھے نہ مرثیہ خواں، لیکن مرثیے کی تاریخ و تفسیر و تنقید پر ان کی نظر گہری تھی، عربی مرثیہ ہو یا فارسی مرثیہ انھوں نے سب کچھ چھان لیا تھا۔ عربی کے عالم نہیں تھے مگر خاصی صلاحیت رکھتے تھے، دوسری زبانوں کے حزینہ رثائی اور رزمیہ ادب کا بھی انھوں نے خصوصی مطالعہ کیا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے مرثیہ نگار، میر انیس کے حالاتِ زندگی اور کلام کا تو شاید ہی کوئی پہلو ایسا رہا ہوگا جو ان کی ہمہ گیر نظر سے بچ رہا ہو۔ انیس کے علاوہ قدیم و جدید مرثیہ نگاروں پر بھی انھوں نے جم کر کام کیا تھا اور مراثی کا ایک نایاب ذخیرہ جمع کرلیا تھا۔
مسعود صاحب نے تحقیق کے لئے مرثیے کا موضوع منتخب کیا۔ غالباً ادب مذہب اور لکھنؤ سے لگاؤ بھی محرک رہے ہوں گے، علامہ شبلی نے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر اس موضوع سے دلچسپی بڑھادی تھی۔ ‘‘موازنہ’’ کی اشاعت کے بعد انیس و دبیر دونوں ہی کے طرفداروں نے اپنے اپنے ممدوحین کی سوانح عمریاں لکھنا شروع کیں، کچھ لوگوں نے ‘‘موازنہ’’ کا جواب بھی لکھا۔ ان میں المیزان کی سی متوازن کتاب بھی تھی اور رد الموازنہ جیسی غیرمتوازن بھی۔ نول کشور پریس سے مختلف مرثیہ نگاروں کے مراثی کی بہت سی جلدیں شائع ہوئیں۔ بعض دوسرے مطابع نے بھی اس میں ہاتھ بٹایا۔ ضمیرؔ، دلگیرؔ، فصیحؔ، خلیقؔ، دبیرؔ، انیسؔ، مونسؔ، رشیدؔ، وحیدؔ، تعشق وغیرہ کا کلام مطبوعہ شکل میں ملنے لگا تھا۔ لیکن اس صنف پر کسی نے جم کر کام نہیں کیا تھا۔ تاریخ مرثیہ پر' دربار حسین' غالباً واحد کتاب تھی لیکن اس تصنیف پر صحیح معنوں میں تاریخ کا اطلاق نہیں ہوتا کچھ جزوی اشارے موازنہ وغیرہ میں بھی تھے۔ سوانح بے حد تشنہ اور پایۂ اعتبار سے ساقط تھے۔ مرثیوں اور سلاموں کے متن اغلاط سے پُر اور الحاقی کلام کی بناء پر مشکوک تھے۔ مسعود صاحب نے اس کام میں نظم و ضبط لانے کا بیڑا خود اٹھایا اور ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کردی۔
انھوں نے ایرانی مرثیہ گوئی پر ہراولی کام کیا ہے۔ افسوس کہ یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوسکی ہے، ممدوح کو مرتے دم تک اس کی اشاعت کا خیال تھا۔ غالباً اب ان کے صاحب زادے نیّر مسعود اس طرف توجہ کریں۔ ہندوستانی مراثی کے قدیم نمونوں کا پتہ نہ تھا۔ انھوں نے بڑی کوشش و کاوش سے قدما کا کلام جمع کیا۔ انھوں نے اپنے ذاتی کتب خانے کے لیے جو ذخیرہ مراثی جمع کیا تھا وہ بے مثال تھا۔ بعض لوگوں نے ان کو توجہ دلائی کہ اس ذخیرے کو کسی بزرگ تر کتب خانے میں محفوظ کردیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ شائقین ادب اس سے فائدہ اٹھاسکیں اور اس کی مناسب دیکھ بھال ہوسکے۔ یہ سوال کئی بار اٹھا لیکن غالباً وہ اس ذخیرے کی جدائی گوارا نہ کرسکتے تھے۔ انتقال سے کچھ دن قبل انھیں بھی یہ خیال ہونے لگا کہ اس ذخیرے کو محفوظ کردینا چاہیے۔ خوش قسمتی سے آل احمد سرور (سابق صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) اور ڈاکٹر محمد حسن (سابق صدر شعبہ اردو جموں و کشمیر یونیورسٹی) دونوں ہی کو یک وقت یہ خیال آیا کہ یہ ذخیرہ اپنی یونیورسٹی کے کتب خانے کے لیے محفوظ کردیں۔
مسعود صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے رائے مانگی کیوں کہ انھیں معلوم تھا کہ علی گڑھ سے لگاؤ کے علاوہ مجھے ریاست جموں و کشمیر سے بھی علاقہ خاص رہا ہے، دونوں ہی نے ایک ہی رقم تجویز کی تھی۔ لیکن ڈاکٹر محمد حسن نے تجویز پہلے پیش کی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ مسعود صاحب ایک طرف تجویز کی اولیت اور اپنے شاگرد کی پیش کش اور دوسری طرف اپنے ایک سابق ہم کار کی پیشکش اور علی گڑھ یونیورسٹی کی علمی اہمیت کے درمیان فیصلہ نہیں کر پارہے ہیں اور اسی لیے میری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ میرے لیے بھی وہی الجھن تھی لیکن میں نے کہا کہ اگر اب ریاست جموں کشمیر میں اردو کا خاصا مقام ہے لیکن وہاں کی یونیورسٹی کو علی گڑھ کی طرح مرکزیت حاصل نہیں ہے۔ تاریخی اور علمی اہمیت کی بناپر مولاناابوالکلام آزاد لائبریری میں زیادہ لوگ اس سے استفادہ کرسکیں گے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ انھوں نے بھی علی گڑھ ہی کے حق میں فیصلہ کردیا اور اب یہ نایاب ذخیرہ وہیں موجود ہے۔ اس ذخیرے میں صرف قدیم ہی نہیں بلکہ جدید مراثی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔
مرثیہ کا دور جدید انیس و دبیر سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور جدید کی بنیاد تو میر ضمیرنے رکھی لیکن اس کی تکمیل دور انیس میں ہوئی۔ مسعود صاحب نے انیس ہی کو تحقیقات کا موضوع بنایا۔ مسعود صاحب بیسویں صدی کے ‘‘انیسیے’’ تھے، آپس میں لڑانے کے لیے نہیں بلکہ وہ انیس کے کھلم کھلا طرفدار تھے۔ اور دبیرکو اس مرتبے کا شاعر نہیں سمجھتے تھے۔ اس معاملے میں وہ علامہ شبلی کے ہمنوا تھے۔ کسی بات میں بھی دبیر کی فوقیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، مثلاً دبیرکے بعض بینیہ مرثیے اچھے سمجھے جاتے ہیں، بی اے کی طالب علمی کے زمانے میں ایک دن میں مسعود صاحب کے دولت کدے پر حاضر ہوا۔ غالباً علی عباس حسینی بھی وہاں موجود تھے۔ باتوں باتوں میں میں نے کہا کہ مرزا صاحب کے بعض سوز کے مرثیے اچھے ہیں۔ فرمانے لگے ‘‘کیسے؟’’ میں نے کہا مثلاً یہ مرثیہ ؎
ع۔ ‘‘جب ہوئی ظہر تلک قتل سپاہ شبیر’’۔ فرمایا۔ ‘‘ہاں اچھا تو ہے، لیکن اس کا جواب انیس نے ایک مطلع میں دے دیا ہے۔’’ پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوگئے۔ شاید میرا ردِّ عمل جاننا چاہتے تھے۔ میں نے خاموشی توڑی ‘‘تو وہ مطلع مرحمت فرمائیے’’۔ کچھ دیر رک کر گویا ہوئے۔
‘‘آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے؟’’ ان کا وہ رک رک کر تاثر بھرے لہجے میں یہ مصرعہ دہرانا اور ایک آہ سرد کھینچنا آج تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ میں نے اس وقت تک انیس کایہ مرثیہ پڑھا نہیں تھا۔ خاموش ہوگیا۔ بعد میں یہ مرثیہ ڈھونڈ نکالا۔ شروع سے آخر تک پڑھ گیا۔ اچھا ہے لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ایک مصرعے پر دبیرکا سارا مرثیہ نثار کردیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ مطلع میں انیس نے بڑی معنویت بھردی ہے لیکن مرثیے کے مقابلے میں ایک مصرعے کو تو نہیں رکھا جاسکتا۔
مسعود صاحب کچھ ایسے موڈ میں آگئے تھے جس میں قدیم شعراء کسی کے اچھے شعر پر اپنا پورا دیوان نچھاور کردیا کرتے تھے۔ ایسی روایت صائب سے لے کر غالب تک اکثر شاعروں کے بارے میں دہرائی گئی ہے۔
انھوں نے انیس کے مراثی، سلام، رباعیاں، خطوط، مناجات سب کو یکجا کیا۔ حیات سے تعلق جہاں جہاں مواد مل سکا۔ بڑی کاوش سے جمع کیا۔ اسلاف و اخلاف انیس پر بھی کام کرتے رہے۔ ‘‘اسلاف انیس’’ پر ان کی کتاب شائع ہوکر اربابِ نظر سے خراج تحسین لے چکی ہے۔ لیکن خود انیس کی زندگی پر وہ کوئی سیر حاصل یا تفصیلی کتاب نہ لکھ پائے۔ صرف روحِ انیس میں مختصر حالات ہیں۔ اس کے علاوہ انیس صدی کے تقریبات کے سلسلے میں انیس پر ایک مختصر رسالہ شائع کیا تھا۔ اس میں بھی کچھ حالات درج ہیں البتہ مختلف پہلوؤں پر کئی مضامین لکھے ہیں۔ حیات انیس پر ان کا وہ جمع کردہ مواد جو شائع نہیں ہوا ہے وہ بہت ہے اور قابل قدر ہے۔ آخر عمر میں ،میں نے کئی بار عرص کرنے کی جسارت کی ،قبلہ یہ بکھرا ہوا مواد کسی طرح بھی سمیٹ دیجیے۔ نوک پلک بعد کے اڈیشنوں میں درست کرتے رہیے گا۔ لیکن میں یہ جانتا تھا کہ یہ ان کا طریقِ کار نہیں ہے اور اس پر ہرگز راصی نہ ہوں گے۔
مجھے یہ ڈر تھا (اور غلط نہیں تھا) کہ ان کے ذہن میں اتنا کچھ محفوظ ہے کہ اس کا سمیٹنا مشکل ہے۔ یہی ان کی مشکل تھی جیسے کہ یہی مشکل قاضی عبدالودود کی بھی ہے۔ ڈھلتی ہوئی عمر، گرتی ہوئی صحت، جواب دیتا ہوا حافظہ، گھٹتی ہوئی طاقت اور کام کرنے کی صلاحیت، یہ تو فطرت کے عطیاتِ پیری ہیں۔ یہ خواہشوں کے پھیلانے کا نہیں بلکہ کام کے سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اتنا مسعود صاحب کو بھی معلوم تھا اور قاضی عبدالودود کو بھی معلوم ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کام سمیٹے کیسے جائیں اور معاونِ کار کہاں سے ڈھونڈھے جائیں؟ آخر میں انسان یہ سوچ کر ہاتھ پاؤں ڈال دیتا ہے کہ ؎
ع۔ فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی! مسعود صاحب پھر بھی ہمت والے تھے کہ انھوں نے قدما کی مرثیہ نگاری پر ‘‘علی گڑھ تاریخ ادب اردو’’ کے لیے ایک باب لکھا۔ پھر ‘‘تحریر’’ دلی میں نادر مواد شائع کرایا اور ‘‘اسلاف میر انیس’’ کی تکمیل کی۔ اب انیس پر انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے یکجا کردینے کا کام رہ جاتا ہے اور یقین ہے کہ نیّر مسعود اسے اوّلیت دے کر مکمل کریں گے۔
انیس کے سلسلے میں مسعود صاحب کا ایک اور کارنامہ مرزا انیس کی تکمیل ہے وہ نصف صدی سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس کام میں ان کے رفیق دیرینہ علی عباس حسینی نے ان کا بہت کچھ ہاتھ بٹایا اور مزار و مکان انیس کی مرمت بڑی حدتک انھیں کی کوشش کی مرہونِ منت ہے۔
اس کے بعد انیس صدی منانے کا خیال بھی انھیں کو سب سے پہلے آیا اور کافی پہلے سے اس کام کی ابتدا کی۔ شروع میں لکھنؤ میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے شدبد شروع کی۔کل ہند پیمانے پر کام کرنا اس کمیٹی کے بس میں نہ تھا۔ خود مسعود صاحب عمر کی اس منزل میں تھے جب وہ صرف تجاویز پیش کرسکتے تھے یا طریق کار معین کرسکتے تھے۔ دوڑ دھوپ کرنا ان کے بس میں نہ تھا۔ دوڑ دھوپ ویسے بھی ان کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اس لیے دلی میں ایک کل ہند کمیٹی کی تشکیل کرنا پڑی۔مسعود صاحب اس کے جنرل سکریٹری منتخب ہوئے۔ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ انیس کے کلام کے صدی اڈیشن صحتِ متن کے ساتھ شائع کیے جائیں۔ یہ کام مسعود صاحب نے اپنے ذمہّ لیا اور نائب حسین نقوی کو اپنا نائب تجویز کیا ،صحت اور ان کے اپنے بکھرے ہوئے کاموں کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ اصرار کہ وہ ہر ایک مسودہ خود دیکھیں گے اور تصحیح کریں گے ناممکن العمل معلوم ہوتا تھا ۔لیکن ان کی بزرگی، انیس سے ان کی وابستگی اور شیفتگی کو دیکھتے ہوئے کمیٹی نے ان کی خواہشات کے سامنے سرتسلیم خم کردیا۔ ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ کام میں بے حد تاخیر ہونے لگی اور چلتی ہوئی گاڑی رکنے لگی، اس سلسلے میں وہ نائب حسین نقوی سے کچھ کبیدہ بھی ہوگئے اور یہ کشیدگی بالآخر کمیٹی ہی سے کبیدگی کی شکل اختیار کرگئی اور صحت کا عذر کرکے وہ کمیٹی سےالگ ہوگئے۔ اس کے باوجود کمیٹی سے ان کی دلچسپی باقی رہی۔
جب میں آخری بار ان سے ملا تو انھوں نے تدوین مراثی کے کام کی رفتار کے بارے میں سوالات کئے۔ اگرچہ یہ کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تھا پھر بھی اس بات سے خوش تھے کہ جیسا بھی ہوگا پچھلے متون کے مقابلے میں شاید یہ کام اچھا ہی ہوجائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب کام چل پڑا ہے۔ سلاموں اور رباعیوں کے مجموعے راقم الحروف نے مرتب کردیے ہیں، کچھ نئے سلاموں اور رباعیوں کا سراغ نائب حسین نقوی نے لگایا تھا۔ میں نے انھیں بھی شامل کرلیا ہے نائب حسین کو بیشتر سلام ریاست محمود آباد کے نادر ذخیرے سے جناب مہاراج کمار صاحب کی عنایت سے ملے تھے اور خود ریاست کو یہ سلام اخلاف انیس سے دستیاب ہوئے تھے۔ اس نئے مواد کی فراہمی کو انیس صدی کی دین سمجھنا چاہیے اور بالواسطہ اس کی فراہمی کا سہرا بھی مسعود صاحب ہی کے سر ہے۔
یہ نیا مواد سلام و رباعی تک ہی محدود نہیں ہے۔ بہت سے نئے مرثیے بھی دریافت ہوئے ہیں اور ان نوادرات مراثی کی ایک جلد الگ سے مرتب ہو رہی ہے۔ مطبوعہ مراثی کی تربیت و تدوین کا کام صالحہ عابد حسین نے انجام دیا ہے۔ یہ کام بھی ابتدائی منزلوں میں مسعود صاحب کی رہبری میں انجام پایا تھا بعد میں اوروں نے بھی ہاتھ بٹایا اور بیگم صاحبہ نے تکمیل کی۔ بیگم صاحبہ ہی نے ناگری رسم الخط میں بھی مراثی انیس کی ایک جلد مراتب کرائی ہے۔ غیرمطبوعہ مراثی کی دریافت بیشتر نائب حسین نقوی کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ یہ کام تیزی سے تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بار بار یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ حیات ہوتے تو ان کاموں کو دیکھ کر انھیں کتنی مسرت ہوتی۔
میں نے ابتدا میں اپنی شاگردی کا ذکر ذرا رواداری میں کردیا تھا۔ اس سلسلے کے چند قابل ذکر واقعات یاد آرہے ہیں۔ مجھے ان کی شاگردی کے صرف دو سال بی اے میں نصیب ہوئے۔ اس کی بھی صورت یہ تھی کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن فارسی جدید کا درس دیتے تھے۔ فارسی میں دو اور استاد تھے۔ سید یوسف حسین موسوی اور عبدالقوی فانی لیکن ان کے درجوں سے میں اکثر غائب رہتا۔ یہ میری زندگی کا وہ دور تھا جب سیاست کے سوا مجھے کچھ سوجھتا ہی نہ تھا۔ فارسی کے درجے سے نہیں بلکہ فلسفے کے درجے سے بھی غیرحاضر ہوجاتا تھا۔ فلسفہ و فارسی دونوں ہی جماعتوں میں تھوڑے سے طالب علم ہوتے تھے اور غائب ہوجانے والا فوراً پکڑ لیا جاتا تھا لیکن میری سیاسی سرگرمیوں کی بناپر اکثر استاد رعایت کرتے اور کبھی کبھی غیرحاضری بخش دیا کرتے تھے۔ مجھے اس دور میں سروپا کا ہوش نہیں تھا، حاضری والوں میں اگر میرا نمبر پہلا نہیں تو پانچ سواروں میں ضرور ہوتا تھا۔ اس وقت خود میں اور اسٹوڈینٹس فیڈریشن کے دوسرے ساتھی اساتذہ سے لے کر وائس چانسلر تک دوڑتے اور حاضری کی کمی کسی نہ کسی طرح پوری کرائی جاتی۔ کچھ اساتذۃ بھی مہربانی کرکے اس آڑے وقت میں حاضر بنادیتے۔ لیکن مسعود صاحب کے یہاں یہ ناممکن تھا، بس اتنی رعایت ضرور کرتے کہ اگر دیر سے بھی آتا تو حاضر بنادیتے اور یہ رعایت بھی صرف میرے لیے مخصوص نہ تھی۔ غرص یہ استادی اور شاگردی بھی دوریوں کا سلسلہ تھی جو چیز قریب لانے والی تھی وہ ادب سے دلچسپی تھی۔
شاگردی بھی دراصل کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک تو درس لینے کی عادت کا نام شاگردی رکھا گیا ہے۔ یہ شاگردی دو برس کی قلیل مدت میں ختم ہوگئی اور چوں کہ ہفتے میں صرف ایک دن ان کے لکچر میں شریک ہوتا تھا، اس لیے یہ مدت تعطیلات وغیرہ کو نکال کر بارہ مہینوں میں تبدیل ہوجائے گی اور ان بارہ مہینوں میں بھی صرف ایک گھنٹے کی شاگردی، ظاہر ہے کہ یہ مدت بہت ہی قلیل تھی۔ لیکن دوسرے شاگردی کی مدت کافی طویل تھی، چالیس سال سے کچھ اوپر مسعود صاحب سے جتنا ادبی خلوص بڑھتا گیا ان کی شخصیت اسی قدر برافگندہ نقاب ہوتی گئی۔ مثلاً میں نے ان سے لفظوں کی پرکھ سیکھی۔ وہ ایک ایک لفظ تول کے لکھتے تھے۔ عبارت کو بار بار پڑھتے ہوئے ضرورت محسوس کرتے تو بار بار ترمیم کرتے۔ انھوں نے یہ سکھایا کہ قلم برداشتہ لکھ لینا ہی کمال نہیں بلکہ ناپ تول کے جانچ پرکھ کے لکھنا بھی کمال ہے۔ لکھنے سے پہلے موضوع کا مطالعہ ضروری ہے۔ جتنا ہی مطالعہ فروعی اور سرسری ہوگا عبارت اتنی ہی ناکافی اور ناصاف ہوگی۔ خیال جتنا ہی آئینہ ہوگا، مواد کی صحت پر جتنا ہی خیال ہوگا تحریر میں اتنی ہی وضاحت ہوگی اور قطعیت بھی ہوگی۔
وہ اردو نثر کے صاحبان اسالیب میں سے ہیں۔ ان کا طرز تحریر قدما میں محمد حسین آزاداور حالی دونوں سے بیک وقت متاثر ہے۔ حالی کا بیانیہ انداز اور رواں عبارت اور آزاد کی شگفتگی خطابت کو ملاکر مسعود صاحب نے ایک متوازن طرز اپنائی۔ خطابت کا پہلو بہت دبا ہوا اور دلائل کے سلسلوں سے مربوط ہے۔ شگفتگی ترتیب کلمات سے پیدا کرتے ہیں لیکن اس طرح کے عبارت آرائی کا گمان نہ ہو اور صداقت لہجہ مجروح نہ ہونے پائے۔ وہ جدید اردو نثر کی طرح جملوں کی شناخت تک میں مغربی اسالیب کی نقالی نہیں کرتے۔ وہ عربی فارسی الفاظ یا اساتذہ کی ترکیبیں مستعار لے کر اردو کے فطری حسن پر مصنوعی آرائشوں کا غازہ نہیں چڑھاتے، ان کا سنبھلا ہوا انداز بیان، شستہ اردو کا اچھا نمونہ ہے۔ ان کے استدلال میں متانت کے علاوہ وضاحت اور منطقی زور ہے۔ استدلال کو قوی تر بنانے کے لیے وہ تفصیل سے گریز نہیں کرتے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی پہلو تشنہ نہ رہ جائے۔ اس کے باعث شاذونادر ان کے یہاں طول کا احساس بھی ہوسکتا ہے لیکن جب مقصد کی وکالت کرنا ہو تو طول سے بچنا ناممکن ہے۔ ادبی چاشنی ان کی ہر تحریر پر چھا جاتی ہے۔ چاہے اس چاشنی کی تہہ کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو۔
ان سے انسان یہ بھی سیکھ سکتا ہے کہ ادب اور تحقیق میں کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ ادیب کے ذہن کے دریچوں کو ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے کہ تازہ ہوا اور روشنی برابر آتی رہے۔ جنھوں نے ان کی تصنیف ‘‘ہماری شاعری’’ کے مختلف اڈیشن دیکھے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ کس طرح برابر اضافے کرتے رہے ہیں اور قابل ترمیم اجزا میں تغیر و تفکیک۔ مضامین میں بھی یہی عمل جاری رہتا۔ پہلے کے شائع شدہ مضامین جب بعد میں کتابی صورت میں آتے تو جگہ جگہ سے پیوند کاری ہوچکی ہوتی۔ قاری کے ساتھ یہ دیانت دارانہ رویہ زندہ رہنے والے ادیب کی پہچان ہے اور انھوں نے یہ دیانت دارانہ رویہ کبھی ترک نہیں کیا۔
وہ محقق کے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ متقدمین سے بھرپور استفادہ کرے، ان کی عزت کرے لیکن ان سے بے جا طور پر مرعوب نہ ہو۔ اس لیے انھوں نے بعض نزاعی ہستیوں کو اپنی تحقیق کا میدان قرار دیا۔ ان میں محمد حسین آزاد بھی شامل تھے اور واجدؔعلی شاہ بھی۔ ان کا طریق کاریہ تھا کہ وہ اپنے موضوع اور حسن تحقیق کی طرف ہمدردی سے متوجہ ہوتے۔ غلطیاں گنانے سے پہلے یہ مان کر چلتے کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی۔ نہ وہ ادیب و شاعر کو فرشتہ مانتے تھے نہ بادشاہ کو۔ انھوں نے واجد علی شاہ اور محمد حسین آزادکے ناقدین کو پڑھا تھا۔ لیکن یہ محسوس کرتے تھے کہ ان دونوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔
‘‘آب حیات کا تنقیدی مطالعہ’’ مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی جچا تُلا مطالعہ ہے اور مسعود صاحب نے وکالت کا حق ادا کردیا ہے۔ بعض اصحاب نے یہ فصا پیدا کرنا چاہی تھی کہ ‘‘آبِ حیات’’ کا مصنف حقائق سے کھیلتا ہے بلکہ حقائق تصنیف کرتا ہے اور اس اعتبار سے اس کا لکھا ہوا سراسر پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔ اس غیرمعتدل رویے کو دیکھ کر غیرمحقق ادیبوں نے غریب آزاد کو بُری طرح نشانہ ملامت بنانا شروع کیا۔ مسعود صاحب نے ‘‘آب حیات’’ کا تنقیدی مطالعہ لکھ کر اس غلطی پر ہم کو ٹوکا۔ پروفیسر محمودشیرانی جیسے صاحب نظر محقق نے بھی اس قسم کی بے اعتدالیوں کی نشاندہی کی۔ اب آزادکی طرف تنقید کا رُخ اتنا معاندانہ نہیں رہ گیا ہے۔
واجدعلی شاہ کو فرشتہ کون کہے گا؟ وہ اپنے بعض گناہوں کے اقراری مجرم ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سرتاپا گناہ تھے یا وہ رنگ رلیوں ہی کے بادشاہ تھے اور رقص و سرود و عیش کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہ تھے۔ یہ صورت تو انگریزوں نے اس لیے بنائی کہ غصب سلطنت اور بربادی اودھ کا جواز نکال سکیں۔ مولوی نجم الغنی (جن کا وابستۂ سرکار انگلشیہ ہونا ڈھکی چھپی بات نہیں ہے) جو کچھ لکھتے ہیں اس پر اکثر افراط و تفریط کی چھاپ ہوتی ہے۔ کچھ تو بات تھی کہ واجد علی شاہ کی معزولی پر عوام نے آنسو بہائے، واجد علی شاہ فنونِ لطیفہ کے بہت بڑے سرپرست تھے، وہ خود بھی نثار و شاعر تھے، ان میں مذہبیت کی طرف میلان کے باوجود سیکولرزم کا جذبۂ حساس تھا۔ وہ فنون حرب کا بھی شعور رکھتے تھے لیکن سازشوں کا شکار تھے اور توہمات میں مبتلا۔ مجموعی طور پر جو تصویر ابھرتی ہے وہ اتنی بُری نہیں ہے۔ جو بعض رنگ آمیز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انھیں کوئی اخلاق عالیہ کا نمونہ بناکر پیش کرنا چاہے تو غلط ہوگا۔ لیکن اگر انھیں کوئی سر تا پا قابل نفرت خصائص کا مجموعہ قرار دے تو وہ اور بھی غلط ہوگا۔ مسعود صاحب نے واجد علی شاہ کے اچھے پہلوؤں پر اپنی تحقیق کا رخ موڑا۔ اس ہمدرانہ مطالعے سے بہت سے وہ حقائق سامنے آئے جن سے لوگ عام طور پر واقف نہ تھے۔ برائیوں کا بڑا انبار پہلے ہی لگایا جاچکا ہے۔ اس کو مسعود صاحب نے نہیں چھوا ،بظاہر یہ غیر متوازن تحقیق سمجھی جائے گی لیکن مسعود صاحب کا جواز یہ تھا کہ وہ پہلے کی غیر متوازن تحقیق میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
دیوانِ فائز دہلوی کی تلاش اور اسکی تدوین و اشاعت مسعود صاحب کا ایک اور یہ کارنامہ ہے۔ شمال ہند میں اس سے پہلے کوئی اور صاحب دیوان شاعر ابھی تک تلاش نہیں کیا جاسکا ہے۔ صرف اولیت ہی نہیں بلکہ مواد کے اعتبار سے بھی یہ دیوان بہت اہم ہے اور جو لوگ بے سمجھے بوجھے، لکھنؤ اسکول اور دلّی اسکول، کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بھی ایک اہم دستاویز ہے۔ یہی حال ‘‘فیض میر’’، ‘‘مجالس رنگیں’’ اور ‘‘فسانہ عبرت’’ اور ‘‘تذکرہ نادر’’ اور ‘‘تذکرہ مبتلا’’ کا بھی ہے۔ انھوں نے ہر قدیم تصنیف کی بازیابی میں ہمیں ایک اچھوتا تحفہ دیا ہے۔ ہزاروں ہی کتابیں ان کی نظر سے گزری ہوں گی لیکن انھوں نے اشاعت کے لیے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔
مسعود صاحب سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ اپنی رائے دوسروں پر لادنا نہیں چاہیے۔ ان سے جب بھی بات ہوتی تو وہ اپنا نقطہ نظر بڑی وضاحت سے پیش کرتے، دلیلیں دیتے، جوابات دیتے لیکن دوسرے کی بات سننے کو بھی تیار رہتے۔ مسعود صاحب پر دوسروں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی تنقیدیں بھی ہوئی ہیں خود میں نے زمانہ طالب علمی ہی میں ایک بار ان سے اختلاف رائے کیا۔ اس پر مجھے مولانا تلہری اور حسینی صاحب دونوں نے ٹوکا کہ تمھیں پہلے ان سے رجوع کرکے شبہات کا ازالہ کرلینا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جب کتاب چھپ گئی یا مضمون شائع ہوگیا تو وہ سب کی ملکیت ہوگیا اور یارانِ نکتہ داں کے لیے صلائے عام ،اب ہرشخص اظہار خیال میں آزاد ہے۔ خود مسعود صاحب نے اس بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا، اگرچہ مضمون اس وقت شائع ہوا جب وہ میرے استاد ہوچکے تھے۔ ان کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد بھی میں نے ‘‘زمانہ’’ کان پور میں ایک مضمون لکھا جس میں دبے لفظوں میں کہیں مسعود صاحب کے بعض خیالات پر ایراد تھا۔ علامہ تلہری کی اچوک نظر اس حصے تک آکر رک گئی۔ انھوں نے کہا کہ حق استادی اس کا متقاضی نہ تھا۔ میں نے جواب دیا کہ جب شاگرد بیا قلم سنبھال لے تو کچھ حق شاگردی بھی ہوجاتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مسعود صاحب تحقیق کے آدمی ہیں۔ برا نہ مانیں گے اور اگر بُرا بھی مانا تو مجھے کبھی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ ہمیشہ اسی شفقت و محبت سے ملتے رہے۔ اکثر خط لکھتے اور مجھے ‘‘عزیز گرامی قدر’’ کہہ کر مخاطب کرتے۔ ادب کے پردوں سے بھی ایسے انسان روز نہیں نکلتے۔
وہ سب کام نپے تلے انداز میں کرتے تھے۔ وہ شیروانی، علی گڑھ کٹ کا پاجامہ، سر پر کبھی بالدار اور کبھی کشتی نما ٹوپی پہنتے تھے۔ گھر پر صرف کُرتے اور پاجامے میں رہتے اور اسی لباس میں عملاً ملتے بھی تھے۔ کبھی کبھی سوٹ بھی پہن لیا کرتے تھے۔ لیکن میں نے انھیں انگریزی ٹوپی پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اس کے برعکس انگریزی سوٹ پر مشرقی ٹوپی ضرور دیکھی ہے۔ مقدرت کے باوجود کار کبھی نہیں رکھی۔ تانگہ رکھتے تھے جس میں جُتے ہوئے گھوڑے کی باگ ڈور ان کے بھائی آفاق کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ بعد میں اس تانگے سے بھی نجات پالی۔
قد لانبا اور بدن گداز تھا۔ داڑھی منڈاتے اور مونچھیں چھوٹی رکھتے تھے لیکن کبھی نیچی نہ ہونے دیتے تھے۔ میں نے ‘‘آپ سے ملئے’’ سلسلہ مضامین میں جو بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع ہوگئے، ان پر بھی ایک مضمون لکھا۔ اس میں مونچھوں کے بارے میں میرے قلم سے یہ نکل گیا کہ وہ تتلی مارکہ مونچھیں رکھتے ہیں۔ اشاعت کے بعد ایک روز مولانا اختر علی نے اس مضمون کا ذکر چھیڑا۔ مسعود صاحب کہنے لگے کہ لکھا تو اچھا ہے لیکن سچ مچ بتائیے کیا آپ کو بھی میری مونچھیں ‘‘تتلی مارکہ’’ لگتی ہیں؟ اختر علی صاحب نے نفی میں سرہلایا تو مسعود صاحب خاموش ہوگئے۔ بعد میں اختر علی صاحب نے مجھے بتایا کہ مونچھوں کی توصیف مسعود صاحب کو پسند نہ آئی۔ کمان سے چھوٹے ہوئے تیر کی طرح فقرہ قلم سے نکل چکا تھا۔ اب تو آئندہ اشاعت ہی میں ترمیم ممکن تھی۔ اس کی نوبت ان کی زندگی میں نہ آسکی۔ میں نے اس موضوع پر ان سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خود مسعود صاحب نے اشارتہً اور کنایۃً اس کا ذکر نہیں کیا۔
مسعود صاحب حسینی اور تلہری کے دوست تھے، لیکن ان تینوں کے مابین احترام بھری دوستی تھی، تو کو کون کہے کبھی ‘آپ’ سے ‘تم’ تک گفتگو نہ پہنچ پائی۔ آپس میں مزاح المومنین بھی ہوتا، سنجیدہ جملے بھی چست ہوتے لیکن لنگوٹیا یار والی کیفیت کبھی پیدا نہ ہوپاتی۔ حسینی اور تلہری مسعود صاحب کو ایک سینئر ادیب تو نہیں مانتے تھے کیوں کہ سنوں میں تفاوت بہت کم تھا لیکن ان کی عزت کرتے تھے اور ان کی برائی کیا، تنقید بھی سننے کو آمادہ نہ ہوتے تھے۔ یہ پرانے اقدارکے پرستار، اس کو بھی شان دوستی کے خلاف جانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ دونوں موقعوں پر جب میں نے کچھ لکھا ،تو میں ٹوکا گیا۔ لیکن حسینی اور تلہری کے برعکس مسعود صاحب نے دوستی، ادب، قومی کا جم سب کے الگ خانے سے بنا رکھے تھے۔ اور وہ کسی ایک شعبے کی دوسرے شعبے میں مداخلت گوارا نہیں کرتے تھے۔
جب میں نے دہلی مرثیہ گویوں پر ‘‘آندھرا پردیش’’ میں ایک مختصر سا مضمون لکھا تو بہت خوش ہوئے اور میری تلاش کی داد دی۔ پھر اپنے یہاں بعض قدیم مخطوطات کی نشاندہی کی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو مجھے نادر بیاضیں دکھائیں، ہاشم اور کرم علی کے مراثی کی زیارت کرائی۔ کہنے لگے کہ ‘‘میرے پاس مسکین کے مراثی کا بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر میں نے نوٹ لینا چاہے۔ فرمایا کہ آپ شوق سے نوٹ لیں لیکن یہ میری زندگی بھر کی تلاش کا نتیجہ ہیں اس لیے ان پر پہلے میں لکھوں گا’’۔ یہ ان کی صاف گوئی مجھے پسند آئی۔ پھر میری معلومات میں یہ اضافہ کیا کہ اسی طرح مراثی میراور بعض دوسرے مراثی پہلے میں نے تلاش کیے لیکن دوسروں نے ان پر مجھ سے پہلے لکھ ڈالا اور لطف یہ کہ وہ مراثی انھیں میں نے ہی دیے تھے۔ میں نے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ ‘‘آپ تحقیق میں لگ جاتے ہیں اور دوسرے کات کے لئے دوڑتے ہیں’’۔ مسکراکر خاموش ہو رہے ۔ غرض اس مسئلے میں مسعود صاحب کے نزدیک دوستی ادب پر حاوی نہیں ہوسکتی تھی۔
قومی کاموں میں بھی صورت حال یہی تھی۔ انیس کمیٹی بنائی گئی خود خزانچی اور علی عباس حسینی سکریٹری بنے۔مسعودصاحب گوشہ نشین اور علی عباس حسنی بے حد فعال۔ انھوں نے دوڑ دھوپ کر پچیس تیس ہزار کی رقم مہیا کرلی۔ اس میں معتد بہ حصہ حکومت ہند کی امداد کا تھا۔ پھر کام شروع ہوا۔ حسینی صاحب نے یہ فرض کرنے میں غلطی کی تھی کہ مسعود صاحب تعمیر کے کام میں مداخلت نہ کریں گے۔ اس سلسلے میں تفصیلات کا علم نہیں کہ کیا ہوا لیکن اتنا معلوم ہے کہ حسینی صاحب نے سکریٹری شپ سے بد دل ہوکر استعفیٰ دے دیا۔
کتابوں کا بہترین ذخیرہ مسعود صاحب کے ذاتی کتب خانے میں تھا۔ گھر پر اگر کوئی آتا تو وہ اس کی اجازت دے دیتے کہ وہیں بیٹھ کر دیکھ لے، لیکن وہ کسی کو بھی کتاب عاریت نہیں دیتے تھے۔ اس میں اندرونی اور بیرونی کی بھی تفریق نہیں تھی۔ ایک بار مجھ سے ان کے داماد مسیح الزماں مرحوم نےبھی دبے لفظوں میں تقریباً شکایت آمیز لہجے میں اس کی تصدیق کی۔ اپنی کئی نادر کتابیں کھو دینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تکلف برطرف، کتابیں عاریت دینا کوئی بہت بڑی خدمت نہیں ہے۔ مالک رام صاحب کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر کسی نے دیانت کا ثبوت بہم پہنچادیا اور وہ کتابوں سے صحیح کام لینے کے قابل بھی ہوا تو وہ بے پس و پیش کتاب دے دیتے ہیں۔ میں نے ان کے ذخیرے سے اکثر استفادہ کیا ہے۔
مسعود صاحب کا شمار ثقہ لوگوں میں تھا۔ وہ اوا مرا و نواہی پر سختی سے عامل رہا کئے ہیں۔ روزوں کا حال معلوم نہیں لیکن نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے۔جوانی کے زمانے میں انھوں نے ڈرامے بھی دیکھے ہیں۔ جوانی جوانی ہی ہوتی ہے۔ انھیں ابتدا سے ڈراموں سے شغف تھا اور یہ شغف بالآخر ان کی اس تصنیف کا سبب بنا جس پر انھیں ساہتیہ اکادمی سے انعام ملا۔ یہ تصنیف دراصل دو تصانیف ‘‘لکھنؤ کا شاہی اسٹیج’’ اور ‘‘لکھنؤ کا عوامی اسٹیج’’ کا مجموعہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس موضوع پر مسعود صاحب نے جی کھول کر داد تحقیق دی ہے۔
مسعود صاحب نے ایسے تو فائز اور میرجیسے قدما پر بھی لکھا ہے لیکن اگر بحیثیت مجموعی دیکھئے تو نوابین اودھ کا آخری دور اور لکھنؤ ہی بیشتر ان کے تصانیف اور تحقیقات کامحور رہے ہیں۔ یہ طریق کار مناسب بھی ہے۔ اگر کسی زمانے یا خاص علاقے کو تحقیق کے لیے چنا جائے تو اس پر سیر حاصل اور ہشت پہلو کام ہوسکتا ہے۔ اگر توجہ چہار جانب ہوگی تو ہر طرف تشنگی کا احساس ہوتا رہے گا۔ انھوں نے وقت اور ماحول منتخب کرلیا اور ایک خط مستقیم پر چلتے رہے۔ اس خط سے پھوٹنے والی تمام شاخوں پر بھی نظر رکھی اور اس سے ایک تنوع پیدا ہوا ، ورنہ کہاں مرثیہ اور کہاں اسٹیج؟
اردو میں تحقیق کے لیے اتنے گوشے پڑے ہوئے ہیں کہ جس طرف بھی نظر اٹھائی جاتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے اور اسی لیے بیک وقت کئی طرف متوجہ ہونا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قاضی عبدالودود کی مثال سامنے ہے۔ اگرچہ غالبیات اور ستواتیات پر انھوں نے زیادہ توجہ کی لیکن وہ جس طرف بھی جھک جاتے ہیں وسعت مطالعہ کے بل بوتے پر وہاں سے کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتے ہیں۔ اس وسعت کی وجہ سے انھوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس کا سمیٹنا ناممکن ہو رہا ہے۔ مسعود صاحب نے کاروبار شوق کو اتنا پھیلایا نہیں تھا، پھر بھی انھوں نے انیس اور واجد علی شاہ پر اتنا مواد یکجا کرلیا تھا کہ اسی کا سمیٹنا ان کے لیے مشکل ہوگیا تھا۔ یہ صدمہ شاید مسعود صاحب کو آخر وقت تک رہا ہو۔
انگریزوں کے زمانہ حکومت کی یونیورسٹیوں میں اردو اور فارسی ہی کیا ہندی سنسکرت اور عربی بھی دوسرے درجے کے مضامین سمجھے جاتے تھے اور ان کے پڑھانے والے عام ذہنوں میں دوسرے درجے کے استاد شمار ہوتے تھے۔ مگر مسعود صاحب کا رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ وہ جس طرف بھی جاتے ان کی عزت دوسروں ہی کی طرح بلکہ بعض اوقات دوسروں سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ وائس چانسلر، رجسٹرار اور خزانچی (مدتوں چندر بھان گپتا خزانچی رہے) بھی اہم امور میں ان سے مشورے لیتے تھے۔ سال کے شروع میں داخلے کے بعد فیس کی معافی کی دوڑ دھوپ شروع ہوتی۔ اردو شعبہ کے ایک ریڈر ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب ہر طالب علم کی درخواست پر سفارش کردیا کرتے، چاہے وہ کسی شعبے کا طالب علم کیوں نہ ہو۔ ہندی اور سنسکرت کے طلبا بھی انپے استادوں سے مایوس ہوکر ان سے سفارش کرالے جاتے تھے لیکن مسعود صاحب سفارش ہی نہ کرتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ محمد حسین صاحب کی سفارش تو سفارش ہی نہ سمجھی جاتی تھی اور مسعود صاحب کی سفارش والے عام طور سے مستحق وظیفہ قرار پاتے تھے۔
مسعود صاحب کو بہت سے اچھے شاگرد ملے جنھوں نے اردو ادب کی دنیا میں خود اپنے لئے ایک جگہ بنالی۔ مسعود صاحب کو اس سے بڑی خوشی ہوتی کہ ان کے شاگرد مفید ادبی خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ وہ ان کی تحریروں پر نظر رکھتے اور کبھی کبھی مشورے بھی دیا کرتے تھے۔ ہمت افزائی بھی کرتے تھے۔ ان کے صاحب زادے ہندوستان و پاکستان کی دو یونیورسٹیوں میں ان کی ادبی جانشینی کر رہے ہیں۔ ان میں نیرّ مسعود سے خصوصیت کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ سب سے بڑا کام فوری طور پر یہ ہے کہ ان کے تحقیقی مضامین اور غیرمرتب مواد کو ترتیب کے ساتھ شائع کردیا جائے۔
تنقید میں مسعود صاحب کا خاص مقام ہے۔ لیکن تحقیق میں اس کا مقام یقیناً بلند تر ہے۔ وہ اچھے شہری اور اچھے انسان تھے، بڑے وضعدار، کشادہ نظر، کم آمیز وسیع الخیال، محتاط، متدین۔ نثر کے رسیا تو تھے ہی، لیکن ابتدا میں شاعری بھی کی تھی اور ان کے نام کے ساتھ ادیب کا اضافہ اسی دور کا یادگار تھا۔ ان کے بعض ابتدائی اشعار میں نے انھیں سے سنے تھے اور دو ایک ‘‘آپ سے ملیے’’ میں محفوظ بھی کردیئےتھے۔ غالباً جوانی میں انھیں سوز خوانی سے بھی شغف تھا اور کبھی کبھی خلوت میں شعر گنگنایا بھی کرتے تھے۔ رنگارنگی میں یک رنگی ہی ان کی زندگی کا طرّہ امتیاز تھی اور اسے مدتوں آنکھیں ڈھونڈتی رہیں گی۔
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.