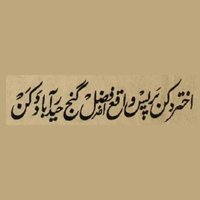आपकी खोज से संबंधित
परिणाम "process"
अत्यधिक संबंधित परिणाम "process"
पृष्ठ के संबंधित परिणाम "process"
समस्त
शब्दकोश से सम्बंधित परिणाम
रेख़्ता शब्दकोश
xiphoid process
xiphoid processxiphoid process
सैफ रोओ ज़ाईदा, सीने की हड्डी के निचले सिरे का ग़ज़रोफ़ी ज़ाईदा, सीने की निचली कुरकुरी हड्डी।
bessemer process
bessemer processbessemer process
(अंग्रेज़ मूजिद सर एच बसीमर (1813-1898) का तरीक़ा: बसीमर तरीक़ा
odontoid process
odontoid processodontoid process
मोहरा-ए-अक़ल्ल गर्दन,दनदानी ज़ाईदा,दूसरे उनकी मनके से आगे निकली हुई हड्डी।